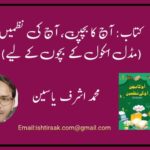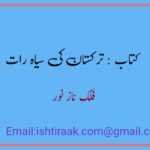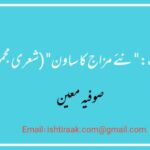خان حسنین عاقب
علامہ محمد اقبال (1877ء–1938ء) اردو اور فارسی شاعری کے وہ تابناک ستارے ہیں جنھوں نے برصغیر کی فکری، تہذیبی اور ادبی فضا میں ایک نئی روح پھونک دی۔ ان کا کلام محض شاعری نہیں بلکہ فکر، فلسفہ، وجدان، اور عمل کی دعوت دیتا ہے۔ اقبال نے اپنے شعری اسلوب کے ذریعے مشرق کے سوئے ہوئے ذہنوں کو بیدار کیا اور ان کے اندر خودی، خوداعتمادی اور یقینِ کامل اور ایمانِ محکم کی آگ بھڑکا دی۔ ان کی شاعری کا سب سے نمایاں وصف اسلوب کی انفرادیت ہے، ایک ایسا اسلوب جو فکری بلندی، روحانی عمق، فنی جدت، اور بیانیہ قوت سے لبریز ہے۔
حالانکہ زیر مطالعہ موضوع کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جسے بالکلیہ طور پر نیا کہا جاسکے لیکن راقم نے کلامِ اقبال کے اس موضوع کو اپنی نظر سے دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اس مختصر سی تحریر میں ہم علامہ اقبال کے شعری اسلوب کی مختلف جہات کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ پیش کریں گے تاکہ یہ دیکھا جاسکے کہ اقبال کے اندازِ بیان نے اردو شاعری میں کس طرح ایک نئے عہد کا آغاز کیا۔
اقبال کے اسلوب کی فکری بنیادیں:
اگر براہ راست موضوع پر گفتگو کریں تو کہا جا سکتا ہے کہ اقبال کے اسلوب کو ان کی فکر سے جدا کرکے نہیں دیکھا جاسکتا۔ درحقیقت ان کا اسلوب ان کی فکری شخصیت کا عکس ہے۔ اقبال کا مشہور زمانہ فلسفہ یعنی پیغام “خودی” کے فلسفے، انسانی آزادی، عشقِ الٰہی، اور عملِ پیہم پر مبنی ہے۔ چنانچہ ان کی زبان، تشبیہات، علامتیں اور لہجہ سب انھی افکار کی ترجمانی کرتے ہیں۔
اقبال کا اسلوب اس لحاظ سے منفرد ہے کہ وہ روایتی عشقیہ شاعری سے ہٹ کر ایک منفرد فکری و روحانی نظامِ حیات پیش کرتا ہے۔ ان کے یہاں شعر برائے شعر نہیں بلکہ شعر برائے اصلاح و تعمیرِ ملت کا نظریہ کارفرما ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں مقصدیت، حرارت اور قوتِ اظہار بیک وقت موجود ہیں۔
شاعری اقبال کے نزدیک محض تفریحِ طبع نہیں، بلکہ ایک روحانی ذمے داری ہے جو شاعر کو قوم کی رہ نمائی پر مجبور کرتی ہے۔
زبان و بیان کی شان اور فصاحت:
اقبال کی زبان نہایت شستہ، بلیغ اور پرشکوہ ہے۔ انھوں نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں پر غیر معمولی قدرت حاصل کی۔ ان کا اسلوب ان زبانوں کے امتزاج سے ایک ایسا لہجہ پیدا کرتا ہے جس میں مشرقی لطافت اور مغربی منطق دونوں یکجا نظر آتے ہیں۔
ان کے اشعار میں الفاظ کا انتخاب نہایت محتاط اور بامعنی ہوتا ہے۔ ہر لفظ اپنی جگہ ایک فکری علامت بن کر آتا ہے۔ ان کی زبان میں ایک خطیبانہ جلال اور روحانی سرشاری پائی جاتی ہے۔
مثلاً:
ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں
ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں
یہ اشعار زبان کی سادگی اور خیال کی وسعت کا حسین امتزاج ہیں۔ یہاں کوئی لفظ غیر ضروری نہیں، ہر مصرع معنی اور تحریک سے لبریز ہے۔
خطیبانہ جوش اور دعوتِ عمل:
اقبال کا اسلوب خطابت اور عمل کی دعوت سے مملو ہے۔ وہ شاعر کم اور ایک مصلحِ قوم زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے کلام میں ایسی ولولہ انگیزی ہے جو قاری کے اندر حرکت پیدا کر دیتی ہے۔
اٹھ کہ اب بزمِ جہاں کا اور ہی انداز ہے
مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے
پھر بادِ بہار آئی، اقبالؔ غزل خواں ہو
غنچہ ہے اگر گُل ہو، گُل ہے تو گُلستاں ہو
تُو خاک کی مُٹھّی ہے، اجزا کی حرارت سے
برہم ہو، پریشاں ہو وسعت میں بیاباں ہو
تُو جنسِ محبّت ہے، قیمت ہے گراں تیری
کم مایہ ہیں سوداگر، اس دیس میں ارزاں ہو
کیوں ساز کے پردے میں مستور ہو لَے تیری
تُو نغمۂ رنگیں ہے، ہر گوش پہ عُریاں ہو
اے رہروِ فرزانہ! رستے میں اگر تیرے
گُلشن ہے تو شبنم ہو، صحرا ہے تو طوفاں ہو
ساماں کی محبّت میں مُضمَر ہے تن آسانی
مقصد ہے اگر منزل، غارت گرِ ساماں ہو
یہ لہجہ کسی مصلح یا خطیب کا معلوم ہوتا ہے جو ساکت روحوں کو بیدار کرنے آیا ہو۔ ان کے کلام میں جوشِ عمل کی یہ کیفیت ان کی انفرادیت کا اہم پہلو ہے۔
علامتوں، استعاروں اور تمثیلات کا نظام:
اقبال نے شاعری میں علامتوں اور تمثیلات کا ایسا مربوط نظام قائم کیا جو اردو شاعری میں اس سے پہلے نظر نہیں آتا۔ ان کے ہاں ہر علامت ایک خاص فکری یا روحانی مفہوم رکھتی ہے۔
شاہین:
اقبال کے نزدیک شاہین محض ایک پرندہ نہیں ہے بلکہ وہ خود دار، آزاد اور بلند پرواز انسان کی علامت ہے۔ وہ کہتے ہیں:
شاہیں کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گِرتا
پُر دَم ہے اگر تُو تو نہیں خطرۂ اُفتاد
نہیں تیرا نشیمن قصرِ سُلطانی کے گُنبد پر
تو شاہیں ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں
تُو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا
ترے سامنے آسماں اور بھی ہیں
خودی:
اقبال کے کلام میں خودی وہ عنصر اور انسانی روح کا وہ جوہر ہے جو اسے خدا سے جوڑتا ہے اور کائنات میں تخلیقی کردار ادا کرنے پر ابھارتا ہے۔ اقبال خودی کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:
خودی کی جلوتوں میں مصطفائی
خودی کی خلوتوں میں کبریائی
زمین و آسمان و کرسی و عرش
خودی کی زد میں ہے ساری خدائی
حکیمی، نامسلمانی خودی کی
کلیمی، رمز پنہانی خودی کی
تجھے گُر فقر و شاہی کا بتا دوں
غریبی میں نگہبانی خودی کی
خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے
مردِ مومن:
اقبال کے نزدیک وہ کامل انسان جو ایمان، عمل، عشق اور علم کا پیکر ہو، مرد مومن کی تعریف پر پورا اترتا ہے۔
اقبال کی شاعری میں مرد مومن کا تصور جا بجا ملتا ہے۔ اس کے لیے وہ مرد حق، بندہ آفاقی، بندہ مومن، مرد خدا اور اس قسم کی بہت سی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ تمام ایک ہی ہستی کے مختلف نام ہیں، ایسی ہستی جو اقبال کے تصور خودی کا مثالی پیکر ہے۔
نقطہ پرکار حق مرد خدا کا یقیں
اور عالم تم، وہم و طلسم و مجاز
عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث
مومن نہیں جو صاحب ادراک نہیں ہے
ہاتھ ہے اللہ کا بندۂ مومن کا ہاتھ
غالب وکار آفریں، کار کشا، کارساز
کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا
نگاہِ مردِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں
غرض یہ مثالی ہستی اقبال کو اتنی محبوب ہے کہ اپنے کلام میں باربار اس کا ذکر کرتے ہیں۔
اس سلسلے میں ایک اہم سوال یہ ہے کہ اقبال نے مرد مومن کا تصور کہاں سے اخذ کیا ہے؟ ان کا یہ تصور محض تخیل کی اپج ہے یا کوئی حقیقی شخصیت ان کے لیے مثال بنی ہے۔ اس سوال کا جواب ان کے کلام کے گہر ے مطالعے کے بعد دیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ ان علامتوں نے اقبال کے اسلوب کو فکری گہرائی اور معنوی تہہ داری عطا کی ہے۔
موسیقیت اور آہنگ:
اقبال کے کلام میں ایک خاص قسم کی موسیقیت پائی جاتی ہے۔ ان کے اشعار میں بحر، وزن اور قافیہ کی بندشیں معنوی ہم آہنگی کے ساتھ چلتی ہیں۔ وہ صوتی حسن کو معنوی تاثیر کے تابع رکھتے ہیں۔ ان کی نظمیں گنگنانے کے لائق اور دل میں اترنے والی ہوتی ہیں۔
کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں
کہ ہزار سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں
خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ
خودی ہے تیغ، فساں لا الہ الا اللہ
یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند
بہار ہو کہ خزاں ، لا الہ الا اللہ
ہزاروں ایسے اشعار مل جائیں گے جو موسیقیت اور نغمگی کے اوصاف سے متصف ہیں۔
اقبال کی فارسی مثنویاں جیسے اسرارِ خودی اور رموزِ بے خودی میں بھی نغمگی اور موسیقیت اپنی انتہا پر نظر آتی ہیں۔ اردو میں بھی طلوعِ اسلام، شکوہ، جوابِ شکوہ اور خضرِ راہ میں یہی آہنگ نمایاں ہے۔
فلسفیانہ اسلوب اور استدلالی انداز:
اقبال کا اسلوب محض شعری تخیل نہیں بلکہ ایک فلسفیانہ استدلال بھی ہے۔ ان کے کلام میں منطق، فلسفہ اور وجدان کا حسین امتزاج ہے۔ وہ سوالات اٹھاتے ہیں، دلیل دیتے ہیں اور پھر عشق و ایمان کی روشنی میں جواب فراہم کرتے ہیں۔
عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے
عشق بے چارہ نہ مُلّا ہے نہ زاہد نہ حکیم
یہاں عقل و عشق کی کشمکش ایک فکری مناظرے کی شکل میں پیش کی گئی ہے مگر انداز ایسا ہے کہ فلسفہ بھی شاعری بن گیا ہے۔ بہ قول اقبال:
اسی کشمکش میں گزریں مری زندگی کی راتیں
کبھی سوز و سازِ رومیؔ، کبھی پیچ و تابِ رازیؔ
عشق کا روحانی اسلوب:
اقبال کے اسلوب کی ایک نمایاں جہت اس کا روحانی رنگ ہے۔ ان کے ہاں عشق محض جذباتی کیفیت نہیں بلکہ ایک کائناتی قوت ہے جو انسان کو خدا کے قرب تک پہنچاتی ہے۔ عشق ہی خودی کو جلا بخشتا ہے۔
عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام
اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا میں
بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق
عقل ہے محو تماشائے لبِ بام ابھی
خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں
مرے مولا مجھے صاحب جنوں کر
خرد نے کہہ بھی دیا لا الہٰ تو کیا حاصل
دل و نگاہ مسلماں نہیں تو کچھ بھی نہیں
اقبال کے نزدیک یہی عشق مردِ خدا کی شمشیر بھی ہے اور یہی عشق مردِ خدا کا زادِ سفر بھی ہے۔ عشق کو محبت کے نام معنون کرتے ہوئے اقبال اپنی نظم "محبت" میں یوں کہتے ہیں:
تڑپ بجلی سے پائی، حور سے پاکیزگی پائی
حرارت لی نفس ہائے مسیحِ ابن مریم سے
ذرا سی پھر ربوبیت سے شانِ بے نیازی لی
ملک سے عاجزی، افتادگی تقدیرِ شبنم سے
پھر ان اجزاءکو گھولا چشمۂ حیواں کے پانی میں
مرکب نے محبت نام پایا عرشِ اعظم سے
ان کے اشعار میں عشق کی حرارت، خودی کی بلندی، اور ایمان کی تازگی ایک دوسرے میں مدغم ہو کر ایک ایسا روحانی آہنگ پیدا کرتی ہے جو قاری کے دل میں سرایت کر جاتی ہے۔ عشق کے بارے میں اقبال کی حتمی رائے ہے کہ:
عشق از فریادِ ما ہنگامہ ھا تعمیر کرد
ورنہ ایں بزمِ خموشاں ہیچ غوغائے نداشت
مشرق و مغرب کے امتزاج کا اسلوب:
اقبال کا ایک اور امتیازی وصف ان کے اسلوب میں مشرقی روحانیت اور مغربی شعور کا امتزاج ہے۔ انھوں نے مغرب کے فلسفے (نطشے، برگساں، گٹے وغیرہ) سے استفادہ کیا مگر ان خیالات کو اسلامی فکر کے سانچے میں ڈھالا۔ ان کے یہاں منطق، علم اور سائنس کی روشنی بھی ہے، اور ایمان، عشق اور روحانیت کی گرمی بھی۔ یہی امتزاج ان کے اسلوب کو وسعت اور آفاقیت بخشتا ہے۔
اقبال نے شاعری کی مختلف اصناف میں اظہارِ خیال کیا اور ہر صنف میں اپنی فکری مہر ثبت کی۔ ان اشعار کو ملاحظہ کیجیے:
یہی فرزند آدم ہے کہ جس کے اشک خونیں سے
کیا ہے حضرتِ یزداں نے دریاؤں کو طوفانی
فلک کو کیا خبر یہ خاکداں کس کا نشیمن ہے
غرض انجم سے ہے کس کے شبستاں کی نگہبانی
(ارمغان حجاز)
ان کی غزلیں روایتی حسن و عشق سے ہٹ کر فلسفیانہ اور انقلابی پیغام رکھتی ہیں۔ نظموں میں فکری تسلسل، بیانیہ قوت اور بلاغت نمایاں ہے. مثنویات میں انھوں نے تصوف اور خودی کے اسرار و رموز بیان کیے۔ ان کا فنی تجربہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ روایت کے پابند رہ کر بھی جدت پیدا کرنے کا ہنر رکھتے تھے۔
اسلوب میں وحدت اور ہمہ گیری:
اقبال کا اسلوب بہ ظاہر مختلف جہات رکھتا ہے، کبھی فلسفیانہ، کبھی خطیبانہ، کبھی عاشقانہ، مگر ان سب میں ایک وحدتِ فکر کارفرما ہے۔ وہ چاہے فارسی میں بات کریں یا اردو میں، نظم لکھیں یا غزل، ہر جگہ ان کی فکری شناخت اور روحانی حرارت نمایاں رہتی ہے۔ یہی وحدت ان کے اسلوب کو انفرادیت اور دوام عطا کرتی ہے۔ اب یہی شعر دیکھ لیجیے:
کیوں چمن میں بے صدا مثل رم شبنم ہے تو
لب کشا ہو جا سرود بربط عالم ہے تو
(شمع اور شاعر؛ بانگ درا)
اقبال کے اسلوب پر متعدد ناقدین نے اظہارِ خیال کیا ہے. سید سلیمان ندوی کے مطابق:
"اقبال کی شاعری میں جوش، ایمان اور یقین کی وہ کیفیت پائی جاتی ہے جو اردو ادب میں پہلے کبھی نہ دیکھی گئی۔"
ڈاکٹر خورشید رضوی لکھتے ہیں:
"اقبال کے ہاں لفظ اور معنی میں ایسا باہمی تعلق ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں کیے جا سکتے؛ یہی ان کی اسلوبیاتی انفرادیت کی بنیاد ہے۔"
پروفیسر یوسف سلیم چشتی جو کلامِ اقبال کے شارح ہیں، کہتے ہیں:
"اقبال کا کلام پڑھنے والا خود کو ایک فکری انقلاب کے اندر محسوس کرتا ہے۔ ان کے الفاظ میں بجلی کی سی تاثیر ہے۔"
یہ آرا اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ اقبال کا اسلوب محض فنی نہیں بلکہ فکری و روحانی انقلاب کی علامت ہے۔
علامہ اقبال کی شاعری اردو ادب کی تاریخ میں ایک سنگِ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کے اسلوب کی انفرادیت ان کے فکری جوہر، روحانی بصیرت، اور فنی مہارت کا نتیجہ ہے۔ ان کے کلام میں الفاظ، معانی، جذبات، اور نظریات اس طرح ہم آہنگ ہیں کہ وہ قاری کے دل و دماغ پر دائمی اثر چھوڑ جاتے ہیں۔
اقبال نے شاعری کو محض اظہارِ جذبات کا ذریعہ نہیں بلکہ تعمیرِ انسان اور احیائے ملت کا وسیلہ بنایا۔ ان کا اسلوب قوموں کو بیدار کرنے والا، انسان کو اس کے مقام سے روشناس کرانے والا اور روح کو بلندیوں کی جانب لے جانے والا ہے۔
یوں کہا جا سکتا ہے کہ اقبال کا اسلوب دراصل ایک فکری انقلاب کی زبان ہے۔ ایک ایسی زبان جو آج بھی انسان کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اپنے اندر کی خودی کو پہچان، کیونکہ یہی تیری اصل قوت ہے۔ ہم اپنی بات کو اقبال کے ان اشعار پر ختم کرتے ہیں.
اے بادِ بیابانی! مجھ کو بھی عنایت ہو
خاموشی و دل سوزی، سرمستی و رعنائی!
غواص محبت کا اللہ نگہباں ہو
ہر قطرۂ دریا میں دریا کی ہے گہرائی
(لالہ ء صحرا۔ بالِ جبریل)
***
خان حسنین عاقب کی گذشتہ نگارش: خلیل جبران کا فلسفۂ جود و سخا

کلامِ اقبال کی اسلوبیاتی انفرادیت
شیئر کیجیے