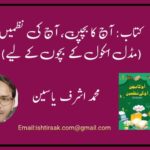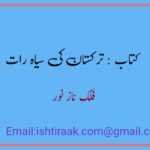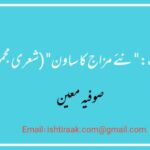محمد فرقان عالم
A-46,3rd Floor,Okhla Vihar,Jamia Nagar,New Delhi-110025
Mobile:8800514745
E-mail:frqnalam@gmail.com
کسی بھی نظریے/تصور کے غیاب میں اگرحالات کی تبدیلی، صورت حال کا تغیر اور سچویشنز کا انتشار شامل ہو تو اس تصور/نظریے کو Theoritically گرفت میں لینے میں دشواریاں درپیش ہو تی ہیں، چیزیں مزید وضاحت طلب معلوم ہوتی ہیں لیکن اگر تبدیلی، تغیر اور انتشار کے دائرے میں ہی اس کے غیاب اور مضمرات کو منکشف کرنے کی جستجو ہو تو شاید تفہیم کے عمل میں آسانیاں میسر ہو سکتی ہیں. ”ما بعد جدید ادب“ کا معاملہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اساسی تصورات پر مرتکز پیش نظر تحریر کو چار حصوں پر مشتمل رکھا گیا ہے تاکہ ان حصوں کے ارتباط سے ایک ایسی تصویر خلق ہو جس کے کینوس پر ”مابعد جدید ادب“ کا تصور رقصاں نظر آئے، ذیل میں اسی کے پیش نظر تحریر کو وسعت بخشنے کی کوشش کی گئی ہے:
(1) ما بعد جدید ادب سے قبل دو توانا نظریات اور اس کے اساسی تصورات
(2) مشرق و مغرب میں مابعد جدید ادب کا پس منظر
(3) مابعد جدید ادب کے تصورات
(4) تخلیقات میں اس کے زیر اثر مستعمل تکنیک
پہلا حصہ
مابعد جدید سے قبل ترقی پسندی اور جدیدیت جیسے نظریات بہت ہی توانا رہے، دونوں کے غیاب میں سماجی اتھل پتھل، نا مساعد حالات، اکتاہٹ، وجودی کرب، سماجی مسائل اور داخلی پیچیدگیاں شامل ہیں، جن کا سبب بیسویں صدی کی ابتدا سے ہی مغربی معاشرے میں آ رہی تبدیلیاں ہیں، ترقی پسندی میں ”جدلیاتی مادیت“ پر مبنی مارکسی نظریات کے زیر اثر سماجی مسائل کو غور و فکر کا مرکز بنایا گیا، یہی وجہ ہے کہ اس کے اساسی تصورات در ذیل قرار پائے:
ٌٌ* سماج۔۔۔۔طاقتور اور کم زور کو بنیاد بنا کر Hierarchy کو احاطۂ بحث میں لینے کی کوشش
* مواد۔۔۔۔مظلوم اور کم زور طبقے کے مسائل و معاملات پر غور
* خارجیت۔۔۔سماج کے ظاہری انسلاکات پر خصوصی توجہ
اس کے بر عکس سارتر کے فلسفے ”وجودیت“ پر مرتکز جدیدیت میں درج ذیل تصورات کو بنیادی حیثیت دی گئی:
* فرد * مواد و ہیئت کی دوئی کا انضمام * داخلیت *ادب کی ادبیت۔ اب اگر دونوں کے اساسی تصورات پر توجہ مرکوز کریں تو واضح ہوتا ہے کہ یہاں مرکزیت ہے، حتمیت ہے اور شاید دونوں میں تغیر پذیر سماج کے مکمل حالات و معاملات نہیں سمٹ سکے ہیں، مابعد جدید تصور میں سب سے زیادہ حملہ اسی مرکزیت، حتمیت اور آفاقیت پر کیا گیا ہے، اس سے قبل کہ اس پر مزید کلام کیا جائے ہمیں مشرق و مغرب کی صورت حال پر توجہ مرکوز کرنی ہوگی تاکہ اس ضمن میں مابعد جدید ادب کے تعلق سے مزید تصویر صاف ہو سکے۔
دوسرا حصہ
مغربی معاشرے بلکہ اس کی سائیکی میں قبل سے ہی قطعیت اور Calculation شامل ہے، Calculatin زندگی کے خارجی معاملات کی تنظیم، تشکیل اور تنسیق کے لیے تو درست ہے لیکن اگر یہ داخلی تعاملات میں بھی پورے طور پر اثر انداز ہونے لگے تو خطرناک بھی ہے، مغربی معاشرے کا المیہ یہ رہا کہ اس کے خارجی عوامل کے ساتھ داخلی تعاملات میں بھی اس کی جڑیں مضبوط ہوتی گئیں. نتیجتاً خالص جذبات پر مبنی انسانی رشتے اس کی زد میں آ گئے اور پھر مغربی
سماج کی جو تصویر ابھری اس کو کچھ اس طرح متصور کیا جا سکتا ہے:
(1) Calculatedاخلاق (2) Artificial جذبات (3) Filtered اقدار۔ ظاہر ہے یہ چیزیں اپنی اصل میں خالص تجریدی ہیں اور تجریدیت روحانیت کا اشاریہ ہوا کرتی ہے جب کہ روحانیت جمالیات و انبساط کو واضح کرتی ہے، ایسے میں جب انسانی زندگی سائنس و ٹیکنالوجی کی حد درجہ اسیر ہوئی اور اس کے اثرات سے بہت ہی زیادہ مستفید بھی، اس کے ذریعے انسانی زندگی کا ظاہر تو منظم ہوا لیکن اس کے باطن کی روح مسمار ہو کر رہ گئی. نتیجتاً انسانی زندگی روحانیت سے عاری ہو کر ایک خشک شے بن گئی، جس میں جمالیات کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا، مشینی زندگی میں ”جمال“ تو ممکن ہے ”جمالیات“ نہیں، جمالیات ظاہری ناپائیدار خوب صورتی کی داخلی پرتوں کا پائیدار لامتناہی سلسلہ ہے، سائنس و ٹیکنالوجی کا یہ دائرہ Micro فارمیٹ اور Maximize فارم میں مزید وسیع ہوا تو اس نے مغربی معاشرے کی قطعیت کو مزید چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیا، اس کی پائیداری تقریباً ختم ہو گئی، اقدار، اخلاق اور تہذیب کو نئے معنی سے آشنا کرنے کی کوشش ہوئی یا اس کی ایسی تقلیب کی گئی جس کو عقل کی کسوٹی اور ذہن کا گوشہ قبول بھی کرے، اس طرح بہ ظاہر انسانی سماج منظم، مرتب، مثقف، مہذب اور خوش دکھنے کے باوجود بہ باطن پائیداری، ٹھہراؤ، گہرائی اور جذبات سے عاری کی منزل پر پہنچتا نظر آیا، اس کے بر عکس مشرق میں جذبات پر قطعیت کا پہرا بٹھانے کی کوشش کم ہوئی اس لیے کہ مشرقی معاشرہ باوجود بعض خامیوں کے (سماجی خارجیت اور انسلاکات کے تناظر میں) جذبات سے متعلق رہا. ساتھ ہی مذہب کی روح سے بھی اس کا رشتہ مغرب کے مقابلے میں بہت حد تک مستحکم رہا، جو بعض جزوی معاملات میں تقدس کی منزل پر بھی پہنچ گیا، اس لیے یہاں تہذیب، اقدار اور اخلاق وغیرہ کی اپنے حقیقی مفہوم میں خاص اہمیت رہی، یہ الگ بات ہے کہ سائنس و ٹیکنالوجی کی حد درجہ جکڑ بندیوں اور ایک خاص Device کے استعمال نے اس پر بھی حملہ کر دیا ہے گو کہ ایک تعداد ہمیشہ اس کمی کو محسوس کر رہی ہے، ایسے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مشرقی معاشرہ ابھی ”کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا“ کی منزل پر نہیں پہنچا ہے تاہم درج ذیل چیزیں مشرقی معاشرے کا بھی حصہ بن چکی ہیں/ بن رہی ہیں:
* انسانی درون میں پیچیدگی * گہرائی کی کمی *دوستی و دشمنی جیسی چیزوں میں بھی ناپائیداری *جھوٹ کو سچ کے لبادے میں ملبوس کرنا *بیشتر معاملات میں Separation کا خاص خیال *صارفی کلچر کا غیر شعوری طور پر حصہ بننا *جذباتی رشتوں میں لطافت کی کمی *فون کالز کے ذریعے جذبات میں قطعیت کی شمولیت *بہ باطن ناپائیدار پیچیدگی، بہ ظاہر منتشر سماجی رویے * ناپائیداری اور لمحے لمحے پر انسانی طبیعتوں کی تبدیلی کی وجہ سے کسی ایک حقیقت/سچ کو تسلیم کرنے میں تامل و تذبذب وغیرہ۔
واضح رہے یہ انسانی سماج کے مبنی بر انسانیت داخلی تعاملات ہیں ورنہ بہ طور فیشن سماج کی ظاہری سطح پر تو اس کے خارجی مظاہر پہلے سے ہی موجود رہے ہیں، اس لیے مابعد جدید بحث کو مواد فراہم کرنے میں اب مشرقی معاشرہ بھی شامل ہے، یہ الگ بات ہے کہ کچھ چیزیں مستثنیات کے زمرے میں داخل ہیں، ایسے میں مابعد جدید ادب میں لا مرکزیت، کسی ایک اتھاریٹی کو تسلیم نہ کرنا، آفاقیت کا فقدان، مقامیت پر توجہ، تکثیریت کے فروغ کی کاوش اور Nostalgic لمحات کا اہتمام وغیرہ چیزیں رائج ہو جاتی ہیں، Nostalgic لمحات کا اہتمام پیشتر بھی تھا لیکن مابعد جدید تصور میں روحانیت اور Asthetics کے بے اثر ہونے، نے اس کی اہمیت میں مزید اضافہ کیا، ماضی بعید کو مستقبل قریب/ بعید میں آمیز کرکے نئی نئی تکنیک وضع کرنے کی کوشش کی گئی، طبیعت کے Filtered اظہار سے زیادہ Unfiltered اظہار پر توجہ مرکوز ہوئی، جس کا اندازہ Filtered فلموں کے مقابلے میں مقامیت پر مبنی بولی، لہجے اور ثقافت پر مشتمل Unfiltered ویب سیریز کی غیر معمولی مقبولیت سے لگایا جا سکتا ہے. یہ دراصل مابعد جدید صورت حال میں انسانی ذہن کی پیچیدگی اور طبیعت کی اکتاہٹ کا نتیجہ ہے۔
تیسرا حصہ
ما بعد جدید تصور کو دوسری عالمی جنگ کے بعد زیادہ فروغ حاصل ہوا، جس کا کسی حد تک اندازہ محولہ بالا سطور سے بھی ہوا، اس کی اصطلاح اولاً آرنلڈ ٹوائن بی (Arnold Toynbee) کی تصنیف A Study of History کی پانچویں جلد (1939) میں استعمال ہوئی تھی، ادبی تنقید میں اس کے استعمال کا باقاعدہ چلن 1950 سے 1970 کے درمیان عام ہوا جس میں شدت 1980کے بعد آئی (1) 1950 سے 1970 کا دورانیہ ساختیات کے استحکام اور کے اثرات کا ہے، جس کی بنیاد میں سوسئیر(Saussure) کا تصور نشان اور اس کی جزئیات (دال، مدلول، لانگ، پارول) کے مباحث شامل ہیں(2). اسی ساختیات کے بطن سے پس ساخیات کا وجود عمل میں آیا، جس میں ”رد تشکیل“ کی تھیوری کو خاص اہمیت حاصل ہے، ”رد تشکیل“ کے مباحث (افتراق، ان کہی، التوا) میں جو بنیادی سوچ پنہاں ہے، وہ ہے”حتمیت“ کی نفی، دریدا نے اسی پر زور دیا، رولاں بارتھ نے اسی وجہ سے مصنف کی موت کا اعلان کیا، جو دراصل اشاریہ تھا کسی بھی اتھاریٹی کو تسلیم نہ کر کے ”خود مختاریت“ کو فروغ دینے کا، پس ساختیات کے زیر اثر کثیر المعنویت پر زور، کلیت کی نفی، حتمیت اور اتھاریٹی کا فقدان جیسی چیزوں پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے، مابعد جدید ادب میں اسی تصور (پس ساختیات) نے اپنے اثرات مرتب کیے، جس کے نتیجے میں مابعد جدید ادب نے ہر طرح کے نظریات، افکار، سچویشنز اور حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ”لامرکزیت“ کو بنیاد فراہم کیا. گو کہ آج تک ماہرین یہی کہتے رہے ہیں کہ اس کی کوئی حتمی تعریف ممکن نہیں ہو پاتی. وجہ بھی یہی ہے کہ اس نے اتنے سچویشنز کو Tackle کرنے کی کوشش کی ہے اور اتنے وسیع تر تناظر کو اپنے دائرے میں محبوس کرنے پر زور دیا ہے کہ اس کو Theorise کر کے Define کرنا مشکل ترین امر ثابت ہونے لگتا ہے، لیکن اگر تمام سچویشنز اور صورت حال کو پیش نظر رکھا جائے تو تفہیم کے عمل میں بہت حد تک آسانی میسر ہو جاتی ہے، جیسا کہ گذشتہ صفحات میں مذکور اب تک کی بحث کے درون سے ظاہر ہوا، اس طرح اس پورے سیاق میں مابعد جدید ادب کے تعلق سے درج ذیل بنیادی تصورات پر توجہ مرکوز کی جا سکتی ہے:
* تکثیریت۔۔۔۔بہت سی مختلف، متنوع اور منفرد چیزیں یکساں طور پر تخلیقات میں شامل ہو سکتی ہیں۔
* مقامیت۔۔۔۔تخلیقی اظہار میں اصول پسندی اور آفاقیت کے بجائے ثقافتی و سماجی رویوں پر زور دینا زیادہ اہم ہے۔
* لا مرکزیت۔۔۔ کسی بھی شے کو دیکھنے کے کئی زاویے ہو سکتے ہیں، کسی ایک زاویے پر اصرار موزوں نہیں ہو سکتا۔
* انتشار۔۔۔۔۔ متن کے درون و بیرون میں ترتیب کے بجائے انتشار، صورت حال اور فضا کے انتشار کا اثر غیر شعوری طور پر متن کے تشکیلی نظام پر بھی ظاہر ہوگا۔
* کھیل۔۔۔۔۔ حساس معاملات کو بھی کھیل اور بے اعتنائی کے پیرایے میں پیش کرنے کی روش، یہ انسان کی داخلی کائنات میں کرب کی انتہائی صورت کا اشاریہ ہے۔
* حتمیت کی نفی۔۔۔ متن سے معانی برآمد کرنے کا حق صرف متن کے درون اور قاری کے ذہنی زاویے کو حاصل ہے، الفاظ کی ترتیب، جملوں کی تشکیل اور ذہن کے زاویے کی آمیزش کے ذریعے ہی متن میں اترنا ممکن ہے، کسی اتھاریٹی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ باہر کے ٹولز کو استعمال میں لاکر متن سے ہم کلام ہو۔
*حقیقت یا کسی بھی شے کے تعلق سے یک رخی رویے کی نفی۔۔۔ حقیقت یا کسی بھی شے کا کوئی ایک Shape نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو کسی ایک نظریے کے تحت کسی خاص ناحیے سے گرفت میں نہیں لیا جا سکتا۔
* عصریت۔۔۔ معاصر انسانی اور سماجی رویے، مسائل،. حالات اور سچویشنزکو پیش نظر رکھنا۔
اس طرح ما بعد جدید ادب کے زیر اثر مندرجہ بالا تصورات پر محیط جو تخلیقات سامنے آتی ہیں/ آئیں گی، ان کو فن کارانہ طور پر پیش کرنے میں بہت سی دشواریاں پیش آسکتی ہیں، تخلیقات میں پیچیدگی کا عنصر غالب ہو سکتا ہے اور تخلیقیت کی جمالیات بھی متاثر ہو سکتی ہے، واضح رہے کہ ما بعد جدید تصور کا سب سے زیادہ اثر فکشن پر پڑا، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ فکشن کا کینوس بڑا ہوتا ہے، اس کی تخلیقیت میں بہت ساری چیزیں یکساں طور پر آمیز ہو سکتی ہیں لیکن کیا بہ ظاہر تخلیقیت کو برتنے کے باوجود تخلیقی پیرایے میں اس آمیزش کی کامیاب ترسیل ممکن ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس صورت میں کوئی بھی تخلیقی فن پارہ، فن پارے کے بجائے فلسفیانہ دستاویز متصور ہوگا، جس میں تخلیقیت کے حقیقی مفہوم کی تلاش جوئے شیر لانے کے مترادف ہوگی، اسی دقت طلب امر کے پیش نظر فن کاروں کی حساسیت نے تخلیقی عمل کے دورانیے میں لاشعوری مواد کے ساتھ شعوری طور پر نئی نئی تکنیک وضع کرنے کو بھی پیش نظر رکھا، یہ نئی تکنیک ماضی بعید کو مستقبل بعید میں، زبانی بیانیے کو تحریری بیانیے میں، حقیقت کو واہمے میں اور فینٹیسی کو حقیقت میں باہم آمیز کرنے کے ساتھ ایک متن کے تصور کی دوسرے متن میں تقلیب کے ذریعے وضع ہوئی جس سے مابعد جدید ادب میں متنوع تکنیک کا بہترین دور شروع ہوا اور بین المتونیت، بلیک ہیومر، واہماتی حقیقت نگاری، فنی آمیزہ، طنز خفی، جادوئی حقیقت نگاری اور میٹا فکشن جیسی فکشن کی تکنیکی اصطلاحات پر زور طریقے سے عمل میں آئیں، پیش نظر مضمون کے چوتھے اور آخری حصے میں انھی اصطلاحات میں سے چند کو تفہیم کے دائرے میں لینے کی کوشش کی جائے گی۔
چوتھا حصہ
* بین المتونیت(Intertextuality)
”بین المتونیت کی اصطلاح فرانسیسی نقاد جولیا کرسٹیوا کے ذریعے 1966 میں وضع ہوئی، Intertextuality لفظ کا ماخذ لاطینی لفظ Intertexto ہے، جس کا مطلب ہے بنتے ہوئے کو باہم ملانا“(3) سادے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک متن کی دوسرے متن میں شمولیت یا ایک متن پر دوسرے متن کی تعمیر بین المتونیت ہے، یہ الفاظ بین المتونیت کے ظاہری معنی تک رسائی کے لیے تو درست ہیں لیکن اس کی جامعیت کو محیط نہیں، اس لیے وسیع تر تناظر میں بین المتونیت کی توضیح یوں ہو سکتی ہے کہ سابقہ متون کی جہات، جزئیات، غیاب (سماجی، ثقافتی، لسانی، تاریخی وغیرہ) اور مضمرات کی متشکل ہو رہے متن میں Deconstruction / تقلیب بین المتونیت ہے، جس میں قاری کی سائیکی میں مضمر متنوع متون کے نقوش اور زیر مطالعہ متن کے درون کی آمیزش بھی شامل ہے، بین المتونیت کے اس وسیع تر مفہوم کو بورخیس کے افسانے A Secret Miracle(مخفی معجزہ) کی روشنی میں مزید بہتر طور پر سمجھا جا سکتا ہے، اس افسانے کے شروع میں سورۂ بقرہ کی آیت نمبر 259 کا یہ ترجمہ ”اور اللہ نے اسے سو برس تک مردہ رکھا پھر زندہ کرکے پوچھا تم یہاں کتنے عرصے تک رہے؟ اس نے جواب دیا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ“ (4) اصل متن سے باہر درج ہے، اسی آیت میں پوشیدہ وقت کے لمحاتی پہلو کو بنیاد بنا کر بورخیس نے محولہ بالا افسانے کو متشکل کیا، افسانے کا کردار ”جارو میر ہلادک“ ایک یہودی ہے، جس کو ہٹلر کے ذریعے موت کی سزا سنائی گئی ہے یعنی اس کو ایک متیعنہ وقت میں گولی مار دی جائے گی، دعا کی شکل میں ”جارو میر ہلادک“ کی آخری خواہش اس نا مکمل ڈرامے کو مکمل کرنے کے لیے ایک سال عطا کیے جانے کی تھی، جس کے کچھ مناظر کا مشاہدہ اس نے خواب میں کیا تھا، اس طرح اس کی سزا کا متیعنہ وقت آن پہنچا اور اس پر بندوقیں تن گئیں، ٹریگر دبنے کے اسی لمحاتی دورانیے میں پل بھر کے لیے ”جارو میر ہلادک“ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، وہ حقیقی دنیا سے خواب کی دنیا کا سفر طے کر لیتا ہے اور جب آنکھیں کھلتی ہیں تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس پل بھر کے لمحے میں اس نے نہ صرف یہ کہ ایک سال گذارا بلکہ اپنے ڈرامے کی تکمیل بھی کر لی، اس افسانے کے متن سے تین چیزیں نمایاں ہوتی نظر آرہی ہیں:
((1 ایک متن کے غیاب میں پوشیدہ وقت کے لمحاتی تصور کی دوسرے متن کی داخلیت میں شمولیت۔
(2) نہ صرف یہ کہ شمولیت بلکہ اس کی رد تشکیل/تقلیب۔
(3) وقت کے عام (خارجی) تصور سے قطع نظر داخلی تصور کو تخلیقی سطح پر برتنے کی کوشش۔ اس طرح مندرجہ بالا سطور سے بین المتونیت کی بہت حد تک وضاحت اور اس کے حقیقی مفہوم تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے۔
جادوئی حقیقت نگاری(Magical Relism)
جادوئی حقیقت نگاری، زبانی بیانیے کو تحریری بیانیے میں بغیر کسی میڈئیٹر کے آمیز کرنا ہے، زبانی بیانیہ ماورائے حقیقی عناصر سے متعلق ہوتا ہے جب کہ تحریری بیانیہ حقیقی لوازم پر مرتکز، اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ ماورائے حقیقت عناصر کا متن میں اس طرح شامل ہونا کہ قاری کا ذہن واقعات میں فوری کوئی فرق محسوس نہ کرے، جادوئی حقیقت نگاری ہے، اس کی عمدہ مثال مارکیز کا ناول One Hundread Years of Solitude (تنہائی کے سو سال) ہے، یہ ناول لاطینی امریکہ کی قدیم تاریخ، روایت، نوآبادیاتی صورت حال کی جزئیات اور اس کے ابعاد پر مشتمل ہے، اس کو متشکل کرنے کے طریقۂ کار کو لے کرمارکیز تذبذب کا شکار تھے، جس میں ناول کی موت کے اعلان (1960) کو خاص دخل ہے.(5) چونکہ مارکیز کے لا شعور میں لاطینی امریکہ کی قدیم تاریخ، زبانی بیانیے کی مستحکم روایت اور اس کے عناصر (لوک کتھائیں، مفروضے، عقائد وغیرہ) شامل تھے جس کی وجہ سے ایک دن اچانک اس کے شعور میں یہ خیال کوندا کہ کیوں نہ اس ناول کو اسی طرز پر متشکل کر لیا جائے جس طرز پر اس کی نانی کہانیاں سنایا کرتی تھیں.(6) اس طرح مارکیز نے لاشعوری مضمرات کو شعوری مواد میں آمیز کرکے ناول نگاری کی دنیا میں شاہ کار ناول کا اضافہ کیا اور جدت کی عمدہ مثال قائم کی، غور کرنے پر اندازہ ہوتا ہے کہ اگرمارکیز نے زبانی بیانیے کی روایت اور اس کے عناصر کو ناول کے متن میں پیش نظر نہیں رکھا ہوتا یا فن کارانہ طور پر ناول کے حقیقی معاملات میں ان کو مدغم کرنے کی کوشش نہیں کی ہوتی تو شاید ناول متشکل ہو جاتا لیکن اس کو وہ مقبولیت حاصل نہیں ہوتی جو ہوئی۔ بلا شبہ دیگر خصوصیات سے قطع نظر خالص ”جادوئی حقیقت نگاری“ کی تفہیم کے لیے بھی ”تنہائی کے سو سال“ کی قرات اہمیت کی حامل محسوس ہوتی ہے۔
* واہماتی حقیقت نگاری (Hallucinatory Realism)
واہماتی حقیقت نگاری، واہمے اور حقیقت کا ایسا امتزاج ہے، جس میں کوئی بھی شے نگاہوں کے کیمرے اور ذہن کے سانچے میں پل پل اپنا زاویہ تبدیل کرتی ہے، واہمہ دراصل ”شعور کی شدید ہیجانی کیفیت کا نام ہے“(7) جب یہ کیفیت شے کی حقیقت میں شامل ہوتی ہے تو ایسی تصویر خلق ہوتی ہے، جس میں تاریکی، نیم تاریکی، دھندلاہٹ اور روشنی پلک جھپکتے ہی اپنا مرکز تبدیل کرتی رہتی ہے، جس سے قاری کسی ایک پل کو فوری گرفت میں نہیں لے پاتا بلکہ وہ اپنے وجود کو اس پورے منظر کے فریم میں مقید کر کے الگ طرح کی طمانیت محسوس کرنے لگتا ہے جس کی ایک اہم مثال کنڈیرا کا ناول Identity (پہچان) بھی ہے، ناول میں محبت کو مرکزیت عطا کر کے ”ژوں مارک“ (مرد) اور ”شانتال“ (عورت) جیسے دو کردار وضع کیے گئے ہیں، دونوں کے مکالمے سے ”مرد اب اور مڑ کر مجھے نہیں دیکھتے“ جیسا جملہ خلق کیا گیا ہے اور پھر اس جملے کے Dimensions پر ناول کے متن کو وسعت بخشنے کی سعی کی گئی ہے، جس کی زیریں لہروں میں مابعد جدید صورت حال اپنی تمام تر جزئیات کے ساتھ متحرک اور رواں محسوس ہوتی ہے، کنڈیرا کا کمال یہ ہے کہ اس نے مواد کو تخلیقیت میں گوندھ کر خواب، حقیقت اور واہمے کے پیرایے میں اس طرح پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ قاری، عمل قرات میں الگ طرح کے تجربے سے دو چار ہوتا ہے، وہ یہ تفریق ہی نہیں کر پاتا کہ کب حقیقت کی دنیا میں تھا، کب خواب کی دنیا میں داخل ہوا پھر کب اور کس طرح حقیقی دنیا میں اس کی واپسی ہوئی؟ آخر میں ناول نگار خود سوالیہ نشان قائم کر دیتا ہے کہ آپ از خود کب؟ کہاں؟ اور کیسے؟ کی نشان دہی اپنے ذہن میں کر لیجیے، واضح رہے کہ اس ناول میں سر رئیلیزم کو زیادہ پیش نظر رکھا گیا ہے لیکن اسی کے بطن میں ”واہماتی حقیقت نگاری“ کو بھی خوب صورتی کے ساتھ تخلیقیت میں گوندھنے پر توانائی صرف کی گئی ہے، آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کنڈیرا کے ناول (Identity) کی قرات سے واہماتی حقیقت نگاری کی تفہیم بہت حد تک ممکن ہے۔
* فنی مخلوطہ/فنی آمیزہ(Pastiche)
ایک متن/ صنف میں دوسرے متون/ اصناف کے الگ الگ حصوں اور ٹکڑوں کی غیر شعوری انداز میں ظاہری سطح پر شمولیت Pastiche ہے، یہاں ”ظاہری سطح“ کا استعمال اس لیے کیا گیا ہے کہ Pastiche میں متن کے ظاہری حصے/ ٹکڑے ہی ایک دوسرے میں شامل ہوتے ہیں، باطنی حصے. (سماجی، ثقافتی، تاریخی، لسانی) بین المتونیت سے متعلق ہیں، Pastiche کو تخلیقیت میں برتنا آسان عمل نہیں، اس کے لیے دوسری اصناف/متون پر باریک نگاہ ہونے کے ساتھ ان کی گہری تفہیم بھی ضروری ہے تبھی ٹکڑے/حصے غیر شعوری طور پر برتے جا سکتے ہیں اور قرات کے دورانیے میں گنجلک کے بجائے روانی کا احساس ہو سکتا ہے، ساتھ ہی انبساطی کیفیات سے سرشاری بھی حاصل ہو سکتی ہے۔
* بلیک ہیومر(Black Humour)
کرب کی انتہائی صورت میں مزاح یا Coolness کی پوشیدہ فضا کو تخلیقیت میں تحلیل کرنا بلیک ہیومر ہے، یہ ایک کیفیت ہے جو محسوسات کی حدتک تو آسان امر ہے لیکن تخلیقی پیرایے میں اس کو کامیابی کے ساتھ برتنا بہت ہی ریاضت کا عمل ہے، اس میں اولاً کرب کی انتہائی صورت کو Calm کر کے تحمل کی زد میں لیا جاتا ہے پھر اس کو مزاح کے پیرایے میں ضبط کے ساتھ پیش کرنے کی سعی کی جاتی ہے اور یہ عمل تخلیق کار کے ذریعے کردار کے درون میں ہی انجام پاتا ہے۔ مندرجہ بالا تکنیکی اصطلاحات سے اس بات کا بہ خوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ”مابعد جدید ادب“ میں ان کی اہمیت کیوں کر ہے اور یہ بھی کہ خود ان اصطلاحات کے درون میں ”مابعد جدید صورتحال“ کی کتنی شقیں پنہاں ہیں، یہاں یہ واضح رہے کہ ”ما بعد جدیدادب“ سے قبل بھی تکنیکی اصطلاحات مستعمل تھیں لیکن ان اصطلاحات کو جس کثرت سے ”مابعد جدید ادب“ میں برتنے کی روش عام ہوئی وہ ماقبل میں نہیں ہو سکی تھی، اس کی وجہ وہی رہی جس کا ذکر پس منظر میں تفصیل کے ساتھ گزرا۔
خلاصہ یہ کہ ”مابعد جدیدادب“ کو قطعیت کے پیرایے میں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ صورت حال کی جزئیات کا ادراک ہو، گہرا احساس ہو اور اس ادراک و احساس کے ساتھ تخلیقی متون میں رواں تکنیکی ٹولز کی وسیع تر تناظر میں تفہیم ہو، اگرایسا کیا جاتا ہے تو ذہن کے کینوس پر ایک ایسی تصویر ضرور ابھرے گی جس میں مابعد جدید ادب کے مضمرات بہ آسانی منکشف کیے جا سکتے ہیں اور اس کی بہترین تفہیم ممکن ہو سکتی ہے، پیش نظر تحریر کو اسی سوچ کے تحت چار حصوں پر مشتمل کرکے متشکل کرنے کی کوشش کی گئی تھی گو کہ اس سے بھی ”ما بعد جدید ادب“ کی شاید کلی تفہیم نہ ہوئی ہو، تاہم ”ما بعد جدید ادب“ کی تفہیم میں معاونت کے لیے ذہن کے پردے پر ایک تصویر ضرور خلق ہو سکتی ہے۔
حواشی:
(1) عتیق اللہ، بین العلومی تنقید، کتابی دنیا، دہلی 2019، ص۔173,175
(2) وزیر آغا، سوسئیر کا نظام فکر. (مضمون) مشتملہ: تنقید کی جمالیات (دوم) مرتبہ: عتیق اللہ، کتابی دنیا، دہلی 2013، ص۔383,385
(3) ناصر عباس نیر، بین المتونیت (مضمون) مشتملہ، بین المتونیت اور بین المتونی تنقید (نظریہ اور اطلاق)، مرتبہ: رغبت شمیم ملک، ایجوکیشنل پبلیشنگ ہاؤس، نئی دہلی 2024، ص۔16
(4) خورخے لوئیس بورخیس، باغ ہزار پیچ، ترجمہ و انتخاب: زیف سید، اثبات پبلیکیشنز، ممبئی 2021، ص۔28
(5) خالد جاوید، اردو فکشن میں جادوئی حقیقت نگاری (لیکچر)، ٹرانسکرپشن: محمد صنوبر عالم، کتابی سلسلہ اثبات (44)، اثبات پبلیکیشنز، ممبئی 2025، ص۔192
(6) مارکیز، امرود کی مہک، ترجمہ: اجمل کمال، مشتملہ، آج مرتبہ: اجمل کمال، یونائیٹیڈ پبلیشرز، مارچ اپریل 1991، ص۔483
(7) محمد داؤد راحت/ ڈاکٹر سید عامر سہیل، واہماتی حقیقت نگاری (پس منظر، بنیادی مباحث اور بنیادی خصوصیات) (مقالہ) مشتملہ: جرنل آف ریسرچ شمارہ1، جلد 29، بہاء الدین زکریا یونیورسٹی، جون 2016، ص۔97
**
آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں : جب تنقید بھی ادب کا ایک حصہ ہے تو اس میں بھی تو ادبیت ہونی چاہیے: غضنفر