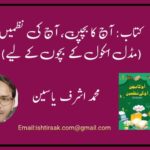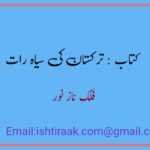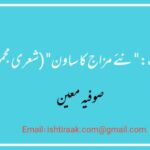شبیر احمد، کولکاتا
انیس رفیع جدید اردو افسانے کے ان ممتاز افسانہ نگاروں میں شمار ہوتے ہیں جنھوں نے اپنا تخلیقی اسلوب خود وضع کیا ہے۔ ان کا پہلا افسانہ ”شاہکار“ 1969 میں شاعر (ممبئی) میں شائع ہوا۔ اب تک ان کے تین افسانوی مجموعے منظرِ عام پر آ چکے ہیں۔ پہلا ”اب وہ اترنے والا ہے“ 1984 میں دوسرا ”کرفیو سخت ہے“ 2002 میں جب کہ تیسرا مجموعہ”گداگر سرائے“ 2016 میں اشاعت سے ہم کنار ہوا۔ پہلے میں 18، دوسرے میں 22 اور تیسرے میں کل 28 افسانے شامل ہیں۔ یہ تمام مختصر ہیں لیکن ان میں ایک افسانہ ”اندر قلعہ“ کافی طویل ہے جسے ناولٹ کے زمرے میں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ یعنی اپنی 55 سالہ تخلیقی زندگی میں انیس رفیع نے صرف 68 افسانے ہی لکھے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انھوں نے اس تخلیقی سفر میں اپنے شعور، ضبط اور مستقل مزاجی کو ملحوظِ خاطر رکھا، اور افسانے کو صرف اظہار کا وسیلہ نہیں، ایک سنجیدہ فکری عمل بھی سمجھا۔ جب انھوں نے باقاعدہ افسانہ نگاری کا آغاز کیا تو اس وقت جدیدیت کا بول بالا تھا۔ لہٰذا وہ اس ادبی رجحان سے متاثر تو ہوئے مگر انھوں نے اسے پورے طور پر قبول نہیں کیا۔ انھوں نے اس روایتی جدیدیت سے ہٹ کر ایک نئی راہ نکالی اور ایسے بیانیے کی طرف متوجہ ہوئے جس کا ڈانڈہ ہیئتی، علامتی، تجرباتی اور نظریاتی طور پر Neo-Left کے دھارے سے جڑتا تھا۔ نیو لیفٹ دراصل طبقاتی جدوجہد پر ہی مکمل انحصار نہیں کرتا بلکہ سماجی انصاف، انسانی حقوق، صنفی برابری، اور ماحولیاتی تحفظ جیسے موضوعات پر بھی توجہ دیا کرتا ہے۔ یہ اْس وقت کی جدید تر فکر کا حصہ تھا۔ اس اعتبار سے انیس رفیع کی افسانہ نگاری ایک نئی قسم کی جدیدیت کا پیش خیمہ بنی۔ یہ وہ جدیدیت ہرگز نہیں جو اْس دور کے ادیبوں پر منطبق کی جا رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے افسانوں میں ایک منفرد فنی و فکری رنگ نمایاں ہے۔
انیس رفیع گہرے تعقلی بیانیے (Profound Intellectual Narrative) اور علامتی اظہار (Symbolic Expression) کے توسط سے عصری مسائل کو انوکھے اور اثرانگیز انداز میں برتنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ وہ فکشن کو محض قصہ گوئی کا ذریعہ نہیں سمجھتے، عصری حسیات (Contemporary Sensibilities) کے تجزیے کا مؤثر وسیلہ بھی مانتے ہیں۔ ان کا کینوس کسی مخصوص دور یا علاقے تک محدود نہیں، وہ تو انسانی وجود، معاشرتی تضادات اور نظریاتی کشاکشی کو وسیع تناظر میں دیکھتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں جہاں طبقاتی تقسیم، استحصالی نظام، اور سماجی جبر کے خلاف خاموش اور گہرا احتجاج سنائی دیتا ہے، وہیں محبت اور رشتوں کی نازکی، انسانی فکر کی پیچیدگی، داخلی خوف اور نفسیاتی بے چینی کا بھرپورعکس بھی ملتا ہے۔ ان کا فن گویا حقیقت اور عصری معنویت کی تہہ در تہہ پرتیں کھولنے کا فن ہے۔ اس ضمن میں ان کے افسانے ”دو آنکھوں کا سفر“، ”پولی تھن کی دیوار“، ”سانپ سیڑھی“، ”مورکھ کالی داس“، ”مسٹر ڈاگ“ کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔
یہاں یہ بات قابلِ غور ہے کہ ان کے یہاں عصری معنویت صرف موضوعات کی سطح پر ہی نہیں ابھرتی بلکہ بیانیے، علامتی اظہار اور اسلوب کی سطح پر بھی منکشف ہو تے ہیں۔ جدید زندگی کی تنہائی، بے بسی، اور تیزی سے بدلتے ہوئے سیاسی و سماجی ڈھانچے اور ان ڈھانچوں کے درمیان فرد کی دبی سہمی نفسیات اور ان سے نکل آنے کی جدوجہد، ان سبھی عوامل کو ان کے افسانے مؤثر انداز میں اجاگر کرتے ہیں۔ ان میں حقیقت پسندی اور علامت نگاری کا ایسا حسین امتزاج ملتا ہے، جو مصنف کے اسلوب کو نہ صرف دل کش اور پْر کشش بناتا ہے بلکہ قاری کو ایک نئے زاویے سے سوچنے پر مجبور بھی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ”ہائی وے“ گہری علامت اور عصری معنویت سے بھرپور ایک افسانہ ہے، جو نہ صرف شہری زندگی کی تیز رفتاری کے تضادات کو آشکار کرتا ہے بلکہ جدید انسان کی بے مائگی اور مادیت پرستی کو بھی آئینہ دکھاتا ہے۔ یہاں بنیادی استعارہ ”ہائی وے“ ہے، جو ترقی، رفتار، اور جدید زندگی کے دباؤ کی علامت ہے۔ افسانے میں رفتار اور ایندھن (Speed & Fuel) کے درمیان رسہ کشی ایک بڑے معاشی مسئلے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہاں معاشی دباؤہے، بڑھتی مہنگائی ہے، نیز زندگی کے تیز تر ہوتے تقاضے بھی ہیں۔ یہ اقتباس دیکھیں:
"اور ہائی وے (Highway) پر گاڑی کی رفتار Speed Limit پھلانگ کر اس بڑھی ہوئی قیمت کو Neutralise کرنے کے در پہ تھی۔ Speed اور Fuel Economy ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہورہے تھے۔ اپنا موپیڈ جو گذشتہ برسوں میں قیمت میں اضافے کی پیداوار تھا، اب منہ تکّو ہورہا تھا۔ موٹرسائکل گھٹ کر موپیڈ بن گئی تھی۔ اب کیا بنے۔ رفتار بھی نہیں بڑھ سکتی ہے۔ اب تو اگلے ماڈل سے ہی کوئی امید رکھی جا سکتی ہے۔ (افسانہ: ہائی وے)
یہ اقتباس عصری معیشت اور روزمرہ زندگی کے مسائل کو طنزیہ انداز میں بیان کرتا ہے، جہاں لوگ اپنی ضروریات اور وسائل کے بیچ توازن برقرار رکھنے کے لیے مسلسل بھاگ رہے ہیں۔ اسی طرح افسانہ ”اب یہاں گدھ نہیں اترتے“ بھی کئی جہتوں میں عصری معنویت سے بھر پور ہے، جہاں تمدنی زوال اور ماضی کی بازگشت صاف سنائی دیتی ہے۔ ویرانہ، جہاں اب زندگی کے آثار نہیں، کسی ماضی کی زندہ حقیقت کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس خطے میں عبادت گاہ تو ہے، مگر اس میں کوئی عبادت کرنے والا نہیں، جیسے ثقافت، تمدن، بستی سبھی نیست و نابود ہو گئی ہوں۔ اور اس طرح یہ عبادت گاہ اس زمین کے زخموں کی علامت بن جاتی ہے۔ یہ اقتباس دیکھیں:
"وہ خوف زدہ ہوا۔ کہیں اس ویرانے اور معبد کا کوئی سحر تو نہ تھا۔ یہ پتھر بنے پرندے اور پیڑ ایسے ہی کسی شراپ کے مارے تو نہیں۔ جنگل، معبد، ویرانہ اس نے ان کے درمیان ربط ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ اپنے ہوش و حواس میں کسی کو معبد میں جاتے نہیں دیکھا تھا۔ دادی کہتی تھی، اور یہ بات بھی دادی نے اپنی دادی سے سنی تھی، کہ اس پار خدا کی بستی تھی۔ اس بستی کے لوگ ہی معبد میں آکر عبادت کرتے تھے۔ تو اب وہ لوگ کہاں گئے؟ اس نے دادی سے وضاحت چاہی۔ جانے کہاں الوپ ہو گئے وہ لوگ؟ کہتے ہیں زمین کھا گئی ان کو۔ (افسانہ: اب یہاں گدھ نہیں اترتے۔)
معبد کے تئیں پرانی نسلوں کے عقائد اور خوف کا ذکر یہ باور کراتا ہے کہ کس طرح ماضی کے اندیشے نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں، بغیر اس کے ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسی طرح گدھوں کا مردہ جانور کھانا اور اسے مکتی سے جوڑنا اس بات کا اشارہ ہے کہ انسان اکثر بنا سمجھے روایتوں سے چپکا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب ان کا عملی وجود بھی باقی نہ رہے تب بھی۔ اسی طرح بانس کے بڑھنے، پھلوں کے پکنے، درختوں کے جلنے اور گدھوں کے مردہ کھانے کی تفصیلات، دراصل زندگی اور موت کے فطری عمل کی عکاسی کرتے ہیں۔ مگر جب فطرت کی مخصوص قوتیں، جیسے گدھ، منظر سے غائب ہو جاتی ہیں، تو انسان بے بسی محسوس کرنے لگتا ہے۔ نیز کہانی میں بچھڑے کی موت کے بعد اس کی تدفین یا مکتی کے روایتی طریقوں کا نہ ملنا گویا اس بات کی علامت ہے کہ پرانے زمانے کی رسومات اب قابلِ عمل نہیں رہیں۔ یہ اقتباس بھی دیکھیں:
"پھر اس نے ٹرک ایک کنارے لگا کر اس سے دریافت کیا۔ ”مال کیا ہے۔ کہاں لے جانا ہے۔“ میرے پاس بچھڑے کا مردہ ہے دارالسلطنت لے جانا ہے“ ”دارالسلطنت!“ ڈرائیور چونکا۔ پاگل— ایک اور طمانچہ دھرا اور ٹرک پر سوار ہو کر روانہ ہوگیا۔ اس طرح وہ مسلسل جھڑکیاں، طمانچے کھاتا رہا۔ دیوانے مزدور کے ہونٹوں پر ہر لمحے خاموش مسکراہٹ رقصاں رہی۔ (افسانہ: اب یہاں گدھ نہیں اترتے)
”دارالسلطنت“ جانے کا فیصلہ اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ اب ہر مسئلے کاحل کسی مرکزی اتھارٹی یا جدید نظام سے وابستہ کر دیا گیا ہے۔
انیس رفیع کا فن ایک ایسی دنیا تخلیق کرتا ہے جو بیک وقت حقیقی بھی ہے اور تجریدی بھی، جہاں کردار، مکالمے، اور فضا سب مل کر ایک وسیع تر فکری اور تہذیبی پس منظرتشکیل کرتے ہیں۔ ان کے افسانے نہ صرف اپنے عہد کی عکاسی کرتے ہیں بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی عمیق معانی کو بھی اجاگر کرتے ہیں۔ ان میں انسانی رشتے، اخلاقی گراوٹ، طبقاتی کش مکش اور سیاسی اتھل پتھل اہم موضوعات کے طور پر ابھرتے ہیں جو ان افسانوں کو اردو ادب میں ایک اہم اور اعلا مقام عطا کرتے ہیں۔”کرفیو سخت ہے“ بھی ایک ایسا ہی افسانہ ہے جو سیاسی اور سماجی جبر کا علامیہ ہے۔ اس میں بیک وقت کئی عصری موضوعات سمو دیے گئے ہیں، جو آج کے تناظر میں بھی معنی خیز نظر آتے ہیں۔ افسانے میں کرفیو اور اندھیرے کو ظالمانہ قوتوں کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جو شہریوں کی آزادی سلب کر رہی ہیں۔ یہ صورتِ حال آج دنیا کے مختلف مقبوضہ علاقوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ اقتباس دیکھیں:
”ہاتھ اوپر“
دونوں نے ہاتھ اوپر اٹھائے اور اسی آواز کی طرف روانہ ہوگئے۔
ہر دو چار مکانوں کے بعد انھیں ملبے نظر آئے اور ان ملبوں سے لہولہان لوگ نکلتے نظر آئے، جہاں کہیں سے بھی اذان کی آواز آرہی تھی وہاں مسجد ضرور ہوگی۔ ہزارہا پل بیتتے چلے جارہے تھے۔ ان لوگوں نے بھی ہاتھ اوپر اٹھائے کتنا لمبا سفر طے کیا۔ مگر ایک نقطہ بھی آیا جہاں انہیں آواز کا آخری سرامل گیا۔ لوگ نماز کے لیے باجماعت کھڑے تھے اور سب کے ہاتھ اوپر اٹھے تھے۔
وہ دونوں بھی جماعت میں کھڑے ہوگئے مگر انھیں حیرت اس وقت ہوئی جب ان کے ہاتھ بھی اوپر سے نیچے نہ آسکے۔ (افسانہ: کرفیو سخت ہے)
یہاں اذان صرف ایک مذہبی فریضہ نہیں، بیداری اور مزاحمت کی علامت بھی ہے، جو ظلم کے خلاف اجتماعی شعور کو جگانے کی ایک کوشش ہے۔ ملبے سے نکلنے والے لوگ اس بات کی علامت ہیں کہ جبر اور تباہی کے باوجود، عوامی مزاحمت زندہ رہتی ہے۔ یہ منظر کئی تاریخی واقعات کی یاد دلاتا ہے، جیسے 2013ء میں مصر کے مسجد رابعہ العدویہ کا سانحہ، جہاں نمازیوں پر گولیاں برسائی گئیں، یا فلسطین میں مسلسل جاری ظلم، جہاں عبادت گاہیں بھی محفوظ نہیں۔ دستورِ ہند سے آرٹیکل 370 ہٹانے کے نام پر کشمیر میں بھی جو کچھ کیا گیا وہ بھی اس منظر نامے کی یاد دلاتا ہے۔ نیز کتابوں کو چمگادڑوں کے ذریعہ گرتے دکھانا، علم و دانش کے زوال کی علامت ہے۔ افسانہ نگار یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر معاشرہ اپنے علمی ورثے کی حفاظت نہ کرے، تو جہالت اور تاریکی اس پر مسلط ہو جاتی ہے۔ یہ اس معاشرے کی طرف اشارہ کرتا ہے، جہاں علم کو دبایا جا رہا ہے، نصابوں کو مسخ کیا جا رہا ہے، اور آزاد خیال لوگوں کو خاموش کرنے کی ہر ممکن کوششیں کی جا رہی ہیں۔ افسانے میں دونوں کرداروں کا ہاتھ اوپر اٹھائے اذان کی سمت جانا اس بات کا استعارہ ہے کہ جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو لوگ کسی رہ نمائی یا اجتماعی عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور آخری منظر میں سب کے ہاتھ اٹھے رہنے کی علامت یہ ہو سکتی ہے کہ شاید جبر اب ان کی سائیکی پر حاوی ہو چکا ہے اور وہ سب کسی بڑی آزمائش میں گرفتار ہیں یا پھر اجتماعی مزاحمت پر آمادہ ہوگئے ہیں۔ بہر کیف، اس کا تعلق ان تحریکوں سے جوڑا جا سکتا ہے جہاں لوگ کسی نظریے کی حمایت میں اجتماعی طور پر کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے 2012ء میں عرب بہار کے دوران مظاہرے، یا 2020ء میں ہندستان میں شہریت قانون کے خلاف اجتماعی احتجاج۔
انیس رفیع کے افسانوں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ خارجی مسائل تک محدود نہیں رہتے، فرد کی داخلی کیفیات اور نفسیاتی کش مکش کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ جدید انسان کی تنہائی، بے بسی اور شناخت کے بحران جیسے موضوعات ان کی تحریروں میں بار بار سامنے آتے ہیں۔ ”لکڑی کے پاؤں والا آدمی“، ”پتامبر“، ریڑھ کی ہڈی“ اور ”ترمیم شدہ اوکتوپس“، ”لوہے کی مٹھی“ اور ”اندر قلعہ“ کو بہ طورِ مثال پیش کیا جا سکتا ہے۔ افسانہ ”پوتول دی“ بھی زندگی، فن، سماجی ناہمواری، اور انسان کے داخلی انتشار کا ایک فکر انگیز اظہاریہ ہے۔ یہاں کلکتہ کے کمہار ٹولی کے پس منظر میں ایک ایسے ہنرمند مورتی ساز کا احوال بیان کیا گیا ہے جو زندگی بھر مورتیاں بناتا رہا، لیکن خود اپنے وجود اور شناخت کی تلاش میں سرگرداں پھرتا رہا۔ یہ کہانی کئی جہتوں پر محیط ہے۔ پہلی جہت کالے میاں سے متعلق ہے جو ایک ماہر مورتی ساز ہے، مگر وہ خود کو محض مزدور سمجھتا ہے۔ اس کی بنائی ہوئیں مورتیاں پنڈالوں میں سجی دھجی نظر آتی ہیں، مگر چند دنوں بعد ہی دریا برد کر دی جاتی ہیں۔ اور اس طرح یہ لمحہ انسانی محنت کی ناپائیداری، زندگی کی بے ثباتی اور فن کے عارضی ہونے کی علامت بن جاتا ہے۔ اسی طرح، یہ افسانہ بستیوں اور پوش علاقوں کی تفریق، امیروں کی آسودگی اور غریبوں کی مشکلات کو طشت از بام کرتا ہے۔ کالے میاں کی بستی کیچڑ اور بدبو سے بھری ہے، جب کہ دوسری طرف نیشنل لائبریری، برلا ہسپتال اور فوجی کمانڈ جیسے مراکز ہیں۔ یہ تقسیم صرف جسمانی نہیں، نفسیاتی بھی ہے، جہاں غربت اور احساسِ کمتری مستقل طور پر موجود ہوتی ہے۔ یہاں یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے باوجود کالے میاں کا ہنر ہندو تہذیب کی پاس داری کررہا ہے۔ ان کی مورتیوں کو لوگ صرف دیکھتے ہی نہیں، ان سے باتیں بھی کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ایک مسلمان مورتی ساز ہندو دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں تراشتا ہے، مذہبی ہم آہنگی اور انسانی فن کے آفاقی ہونے کی علامت ہے۔ مزید برآں، اس میں پوتول دی اور رضیہ جیسے دو مضبوط نسوانی کردار بھی ہیں۔ پوتول دی کمہار ٹولی کے حقوق کے لیے لڑتی ہے، جب کہ رضیہ ایک ایسی عورت ہے جو حالات کی سختیوں کے باوجود مسکراتی رہتی ہے۔ پوتول دی کا اسٹبلشمنٹ سے بغاوت اور رضیہ کا ضبط و تحمل، دونوں ہی، عورت کی جدو جہد کی مختلف شکلیں ہیں۔ اس افسانے کا انجام دیکھیں:
"منتری جی کے آنے کا امکان جب موہوم ہو گیا تو فیصلہ ہوا کہ علاقے کے سر کر دہ لیڈر بودھن کی رسم ادا کریں گے۔ اعلان سنتے ہی تھانہ ان چارج ان کی طرف لپکا۔ پھر انہیں Escort کر کے مورتی کے قریب لے آیا۔ انہوں نے مورتی کلا اور مذہبی تہواروں پر ایک نصیحت آمیز بھاشن دیا۔ پردہ کشائی کی رسم ادا کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ پردہ اٹھتے ہی جیسے تھانہ ان چارج اور وہ سکتے میں آگئے۔ دیوی کا چہرہ جلال میں تھا اور ہاتھ سے ترشول چلنے ہی والا تھا۔ دونوں نے اپنے ہاتھوں کی ڈھال بنائی اور اپنے اپنے سینے ڈھک لیے۔ مگر دوسرے لمحے ہی ڈھاک کی آوازکے ساتھ دونوں کی فلک شگاف آواز گونجی— ”چھما دیوی — چھما رضیہ!“ (افسانہ: پوتول دی)
افسانہ فسادات کی وحشت کو بے نقاب نہیں کرتا، بلکہ معاشرے کے ضمیر پر کاری ضرب بھی لگاتا ہے۔ رضیہ کا چہرہ، جو دیوی کی مورتی میں منکشف ہوتا ہے، وہ دراصل سوالیہ نشان بن جاتا ہے۔ پوچھتا ہے، کیا مذہب اور انسانیت دو متضاد حقیقتیں ہیں؟ کیا مندروں میں دیویوں کے پجاری، حقیقی زندگی میں ایک رضیہ کو انصاف دینے سے قاصر ہیں؟ یہ انجام قارئین کے ذہن میں گہری چھاپ چھوڑ جاتا ہے کہ شاید ہر رضیہ، ہر معصوم، جو ظلم کا شکار ہوتا ہے، کسی نہ کسی صورت میں لوٹ کر آہی جاتا ہے— چاہے ضمیر کی خلش بن کر، یا پھر ایک جلالی چہرے والی مورتی کے روپ میں!
انیس رفیع کے افسانوں میں سیال بیانیہ نہیں ہوتے، بلکہ تلخ اور کھردری حقیقتوں کے ٹھوس تہہ دار عکس ہوتے ہیں۔ پھر بھی کچھ افسانے ایسے ہیں جنھیں سیال بیانیہ کے زمرے میں رکھا جا سکتا ہے، ”لوہے کی مٹھی“، ”مولا دادا آئیں گے“، ”اندر قلعہ“،۔ مثلاً افسانہ ”اب وہ اترنے والا ہے“ ایک تلخ حقیقت بیان کرتا ہے کہ کس طرح حکمراں طبقہ عوام سے ان کا سب کچھ چھین کر بھی ان کے جذبات اور امیدوں کے ساتھ کھلواڑ کرتا رہتا ہے۔ افسانے کا انجام ایک المناک حقیقت کو ظاہر کرتا ہے، جب عوام کے پاس نہ کوئی سوال بچتا ہے، نہ احتجاج کی طاقت، نہ بولنے کے لیے ہونٹ! اور تب حکمراں طبقہ سارا کھیل ہی ختم کر دیتا ہے۔ یہاں افسانہ نگارکا اسلوب انتہائی تمثیلی و استعاراتی ہے۔ پوری کہانی ہی علامتی سطح پر قائم ہے۔ مثلاً ”اترنے والا“ ایک ایسا کردار ہے جو کسی سیاسی رہ نما، مذہبی پیشوا یا طاقتور ادارے کی نمائندگی کرتا ہے، جو عوام سے جھوٹے وعدے کرتا ہے اور انھیں دھوکے میں رکھتا ہے۔ اسی طرح ”مسکراہٹ کی تھیلیاں“ درحقیقت جھوٹے خواب اور امیدیں ہیں، جو حکمران عوام کو دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں کبھی وہ خواب شرمندۂ تعبیر ہوتے ہیں اور نہ وہ امیدیں ہی پوری ہوتی ہیں۔ ”بازو، ٹانگیں، آنکھیں، اور ہونٹ دینا“ استحصال کی علامت ہے، جہاں عوام اپنی ذہنی، جسمانی اور جذباتی آزادی حکمرانوں کے ہاتھوں گنواتے رہتے ہیں۔ نیز ”قطار“ بھی اطاعت اور فرماں برداری کی علامت ہے، جو جابرانہ نظام میں عوام کی بے بسی ظاہر کرتی ہے۔ یہ اقتباس ملاحظہ فرمائیں:
"اترنے والا ایک مدت بعد پھر اتر آیا۔ اس بار اس کے لہجے میں بڑی ہمدردی اور جملوں میں دکھ کی آمیزش تھی…
”آپ سب نے ہماری طرف سے ملنے والی مسکراہٹ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کردیا۔ آپ سب ہمارے سچے اور مخلص پرستار ہیں۔ یقین کیجیے ملنے والی مسکراہٹ ضرور ملے گی…
…مگر اب جبکہ آپ اندھے، لنگڑے اور نہتے ہوچکے ہیں اور اس قابل بھی نہیں رہے کہ قطار سے نکل کر اپنے حصے کی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر لے سکیں اور دوسروں کی مسکراہٹ دیکھ سکیں اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب اپنے اپنے ہونٹ ہمارے حوالے کردیں ہم انھیں اوپر چوٹی پر لیجائیں گے اور اعلیٰ قسم کی مسکراہٹ ان پر منڈھ کر انھیں آپ کے پاس واپس بھیج دیں گے۔“
سب نے اپنے اپنے ہونٹ پیش کردئیے۔ اترنے والا ہونٹوں کا قافلہ لیکر اوپر چڑھ گیا…اور ایک دن یہ اعلا ن…
…بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کی قوت سماعت بے حد وفادار ہے۔ آپ لوگوں نے برابر کہی جانیوالی باتیں غور سے سنیں اور ان پر عمل کیا۔ لہٰذا آپ یہ جان لیں کہ اترنے والا اب کبھی نہیں اترے گا کہ اب آپ کے پاس مسکراہٹ کے لیے ہونٹ بھی نہیں رہے۔
براہِ کرم آپ سب قطار توڑ دیں۔ جلدی کریں – بھیڑ نہ لگائیں!!!“ آخری موقع (افسانہ: اب وہ اترنے والا ہے)
افسانہ نگار بڑے طنزیہ انداز میں جابر اور استحصالی نظام پر تنقید کرتا ہے، اور یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ اب بھی وقت ہے جاگ جاو، جھوٹے خوابوں کے سحر میں گرفتار نہ رہو۔ ویسے یہ کہانی کسی مخصوص وقت یا جگہ سے جْڑی نہیں، یہ ہر اْس معاشرے پر منطبق ہو سکتی ہے جہاں عوام کو دھوکے اور استحصال کے ذریعے بے بس بنایا جاتا ہے۔ اور آخر کار عوام کی یہ حالت ہوجا تی ہے کہ وہ اپنا سب کچھ لْٹا کر بھی مسکراہٹ کی آس میں قطار باندھے کھڑے رہتے ہیں، یہاں تک کہ مسکرانے کے لیے ان کے پاس ہونٹ بھی نہیں بچتے۔
انیس رفیع کے یہاں بعض ایسی دیہاتی عورتوں کے کردار بھی نظر آجاتے ہیں، جوظلم و جبر، اور انصرامی طاقت سے ٹکرا جانے کا حوصلہ رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر افسانہ ”غروب سے پہلے“ میں ایک حاملہ عورت اور ”بھگ جگنی“ میں بھگ جگنی کا کردار نہ صرف عورت کی علامت ہیں بلکہ بغاوت، جبر کے خلاف مزاحمت اور مظلوم طبقے کی اجتماعی آواز بھی ہیں۔ دونوں افسانے ایسی دیہاتی عورتوں کے گرد گھومتے ہیں جو مظلومیت، مزاحمت اور نسلی تفریق کے تانے بانے میں جکڑی ہوئی ہیں۔ یہاں دیہاتی سماج میں ہونے والے ناانصافی، جابرانہ نظام، عورتوں کے استحصال اور جاگیردارانہ بندوبست کے خلاف بغاوت کے انگارے دہکتے ہیں۔ دونوں ہی عورتیں ہمت اور حوصلے کی مضبوط علامتیں ہیں جو نہ صرف مقامی اداروں بلکہ پورے استحصالی نظام کو چیلنج کرنے کا عزم رکھتی ہیں۔
انیس رفیع کی افسانہ نگاری کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ ان کے یہاں گاؤں شہر، گلیاں، سڑکیں سب جیتے جاگتے سانس لیتے نظر آتے ہیں۔ گاؤں، جو دن میں جامد اور مردہ سا لگتا ہے، رات میں ایک غیر مرئی قوت کے زیرِ اثر آجاتا ہے، جہاں بھگ جگنی ایک علامتی کردار کے طور پر ابھرتی ہے۔ ایسے علامیے میں افسانہ نگار اکثر تمثیلی انداز اپناتا ہے اور یہ باور کراتا ہے کہ کس طرح دبی کچلی صنف نازک بھی اگر ایک نقطے پر جمع ہوں تو پورے استبدادی ڈھانچے کو جڑ سے ہلا سکتی ہیں۔ یہاں زبان کی جادوگری بھی انھیں دل پذیر بنادیتی ہے۔ یہ اقتباس دیکھیں:
"عورت ایک بار پھر چلائی اور پیٹ پکڑ کر گاؤں کی طرف بھاگی۔ سپاہی نے پیچھے سے رائفل کی بٹ ماری۔ وہ اوندھے منھ گرگئی۔ منھ اٹھایا تو خون اس کے ہونٹوں پر تھا۔ وہ دہاڑی۔
”چھوڑدے جانے دے نہیں تو انرتھ ہوجائے گا۔“سپاہی نے پھر رائفل کی بٹ اس کی طرف اٹھائی۔
”کیا ہورہا ہے جوان؟“ ایک کرخت آواز آئی۔
”سر یہ گاؤں میں گھسنا چاہتی ہے۔“ رائفل کی سلامی دیتے ہوئے وہ بولا۔
”جانے دو اسے آپریشن سماپت ہو گیا۔“
حکم سنتے ہی عورت کانٹے تڑپ گئی اور گاؤں کے اندر بھاگتی چلی گئی۔ سپاہی من ہی من بولا۔
”بائی کے جھونک میں بھاگ رہی ہے۔ سالی، گربھ لے کر اتنا کودے گی۔“
بھگ جگنی اپنے گھر کے پچھواڑے سے ہوتے ہوئی گھنی بسواڑی میں پہنچ چکی تھی۔ بن بلار سب وہیں تھے۔ اس نے اپنے پھولے ہوئے پیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ بندھی ہوئی گرھیں کھولی اور ایک ایک کرکے پیٹ پر بندھی ہوئی چیزیں نکالنے لگی۔ دیسی پستول، چینی کٹے، بارود۔ نہ جانے کیا کیا۔ اس نے ایک بار پھر. پیٹ پر ہاتھ چلایا۔ پیٹ پچک چکا تھا۔ وہ اپنی ٹیوب بے بیوں کی Safe delivery پر بہت خوش تھی۔ بہت ہی خوش! (افسانہ: بھگ جگنی)
یہاں جاگیردارانہ استحصال، عورت کی بے بسی اور معاشرتی بے حسی جیسے موضوعات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ کہانی میں عورت کے استحصال کی عکاسی محض ایک فرد کا دکھ نہیں، ایک اجتماعی المیہ بھی ہے۔
انیس رفیع کا طرزِ بیان اور اسلوب اردو افسانے میں ایک منفرد شناخت رکھتا ہے۔ وہ حقیقت نگاری، علامت نگاری اور نفسیاتی تجزیے کو ایک نئے زاویے سے برتتے ہیں۔ ان کا اسلوب بیانیہ محض واقعات کی ترتیب نہیں، بلکہ کہانی کے پس پردہ وجودیاتی مسائل کا آئینہ دار بھی ہے۔ مثال کے طور پر افسانہ ”اب وہ اترنے والا ہے“ اور ”کاٹھ کے پتلے“ میں بار بار جملوں کی تکرار، خطابی انداز، اور براہِ راست مکالمے کا استعمال قاری کو ایک پْراسرار اور ہیجان انگیز کیفیت میں مبتلا رکھتا ہے۔ ’اب وہ اترنے والا ہے‘… جیسے جملے بار بار دہرا کر ایک سنسنی خیز فضا قائم کی گئی ہے۔ راوی کا انداز بھی خاص ہے۔ یہ کہانی اجتماعی خودکلامی کی صورت تمثیلی پیرایے میں بیان کی گئی ہے، جو قاری کو براہ راست مخاطب کرتی ہے اور اسے بھیڑ کا حصہ بننے پر مجبور کرتی ہے۔ اسی طرح افسانہ ”کاٹھ کے پتلے“ میں بھی افسانہ نگار نے ایک خاص تکنیک اپنائی ہے، جہاں بیانیہ ایک مسلسل دہرائے جانے والے جملے – ”یہ دکان ہے، اس دکان میں کاٹھ کی بنی ہوئی چیزیں بکتی ہیں“… کے ذریعے آگے بڑھتا ہے۔ یہ نہ صرف افسانے کی ساخت کو مربوط رکھتا ہے بلکہ ایک خاص Rhythm اور شاعرانہ آہنگ بھی پیدا کرتا ہے، جو قاری کو کہانی کے بہاؤ میں کھینچ لاتا ہے۔ اسی طرح ”الہ دین لیمپ اور عطر کی پیٹی“ کی زبان بھی شاعرانہ اور تاثراتی ہے، جس میں ماضی اور حال کے درمیان خوب صورت جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں۔ فلیش بیک تکنیک کا استعمال عمدگی سے کیا گیا ہے، جو قاری کو بھولا کے ساتھ گاؤں کے خوش بو دار ماحول میں لے جاتا ہے اور پھر یکدم کلکتہ کی بے روح زندگی میں واپس لے آتا ہے۔ جملوں میں ایسی روانی اور مناظر میں ایسی دل کشی ہے کہ قاری کہانی کے ہر لمحے کو اپنی آنکھوں کے سامنے محسوس کرتا ہے۔ افسانہ ”نیل کنٹھ کا اصل“ میں مصنف نے سادہ مگر پراسرار اسلوب اپنایا ہے جو کہانی کے اندرونی تنازع کو ابھارتا ہے۔ زبان عام فہم مگر شگفتہ اور چابک دستی سے لکھی گئی ہے، جو قاری کو مسلسل اپنی گرفت میں لیے رکھتی ہے۔ یہ افسانہ جدید سائنسی تصورات، تجسس، اور علامتی بیان کے امتزاج کا بہترین نمونہ ہے۔ کہانی کا آغاز ہی ایک حیران کن صورتِ حال سے ہوتا ہے، جہاں ڈاکٹر نیل کنٹھ ایک ہی وقت میں مختلف جگہوں پر دکھائی دیتا ہے۔ یہ تجسس کہانی کے اختتام تک برقرار رہتا ہے۔”نیل کنٹھ کی نقل“ دراصل آج کے جدید دور میں انسان کے کئی چہروں، کرداروں اور شناخت کا استعارہ ہے۔ آج کے دور میں انسان ایک ہی وقت میں مختلف جگہوں پر مختلف طریقوں سے موجود ہوتا ہے—چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، دفتری دنیا ہو، یا ذاتی زندگی! افسانے میں کرداروں کے مکالمے بے ساختہ، حقیقت پسندانہ اور مختصر ہیں، جو کہانی کی رفتار تیز تر رکھتے ہیں اور قاری کو اکتانے کا موقع نہیں دیتے۔ نیز افسانے کا طرزِ بیان، بیانیہ اور مکالماتی انداز کا حسین سنگم ہے۔ واقعات کو اس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے کہ ہر لمحہ ایک معمہ معلوم ہوتا ہے، جس کی گرہ آخر میں جا کر کھلتی ہے۔
انیس رفیع کا اسلوب علامتی اور تجریدی ہونے کے باوجود بیانیہ قاری کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ وہ اپنے افسانوں میں جدید عہد کے مسائل، معاشرتی زوال، نفسیاتی پیچیدگیوں اور انسانی بے بسی کو ایسے استعاروں اور علامتوں میں پیوست کرتے ہیں جو نہ صرف فن کارانہ چابک دستی کے مظہر ہیں بلکہ وہ فکریاتی سطح پر بھی قاری کو جھنجھوڑتے ہیں۔ گویا وہ انسانی وجود کی الجھنوں، سماجی انتشار، اور ثقافتی انحطاط کی تجریدی تصویر ہوں۔ وہ اکثر عام فہم بیانیہ سے گریز کرتے ہیں۔ رمز و علامت کی زبان برتتے ہیں، جس سے کہانی کی معنویت مزید دبیز اور تہہ دار ہوجاتی ہے۔ ان کے افسانوں میں کرداروں کی بجائے صورتِ حال زیادہ واضح ہوتی ہے، جو جدید دور کی بے چینی، بے سمتی اور بے چہرگی کی عکاس ہیں۔ اس لحاظ سے ”نصف بوجھ والا قلی“، ”پہاڑ ٹوٹ رہا ہے“، ”پانی پانی شرم“،”پانچ مردے“، ”ملنگ باباوں کی پکنک“ اور”ذوالنون“ وغیرہ کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ ”ذوالنون“ علامتی اور تجریدی پیرایے میں لکھا گیا ایک افسانہ ہے، جہاں واقعات کی ظاہری سطح کے نیچے دقیق معنویت کی کئی زیریں لہریں بہتی ہیں۔ سپن مہرا کا کردار ایک ایسے شخص کا استعارہ ہے جو اپنے ماضی، ضمیر، اور شناخت کے بوجھ تلے دب چکا ہے۔ اس کی کوٹھری میں پڑی ہوئی ”لاش“ اس کے اندر کے مردہ احساس، ماضی کے بھیانک تجربے یا پھر کسی گناہ کی علامت ہے، جسے وہ دوسروں کے حوالے کرنا چاہتا ہے کہ وہ اس سے نجات پا سکے۔ وہ ہر کسی سے کہتا ہے کہ کوئی اس لاش کو اٹھا کر پھینک دے، مگر کوئی بھی شخص ایسا کرنے کو تیار نہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان اپنے اندر کے گناہ، ماضی کے صدمے یا اخلاقی زوال سے خود چھٹکارا نہیں پا سکتا، اور نہ ہی دوسروں سے اس کی توقع کر سکتا ہے۔ اسی طرح ”سات گھڑے پانیوں والی عورت“ میں امرود صرف پھل نہیں، ایک علامتی شے بھی ہے۔ عورت کے لیے امرود کا کھانا خودکشی کے مترادف ہے کیونکہ یہ ”سات گھڑے پانی“ کی خاصیت رکھتا ہے اور وہ اپنے ہی پانی میں ڈوب جانے سے ڈرتی ہے۔ یہ دراصل اس کے جذباتی بوجھ اور عصری جبر کا اشاریہ ہے جو اسے گھٹن اور تنہائی میں مبتلا رکھتا ہے۔ یہاں بھی استعارات اور علامات کا کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ مثلاً ”سنگ میل“ جو عورت کی زندگی میں ایک مستقل حقیقت کی علامت ہے، جہاں بیٹھ کر وہ ہمیشہ انتظار کرتی رہتی ہے۔ ”سڑک“ جو مسلسل تغیر پذیر زندگی کی علامت ہے، جو کبھی کسی کے لیے نہیں رکتی۔ نیز ”امرود کا باغ“ جو عورت کے جذبات و خواہشات کی علامت ہے، جو وقت کے ساتھ ویران ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح ”سوکافا“ کی سب سے بڑی خوبی اس کا علامتی انداز، استعاراتی گہرائی اور تجزیاتی اسلوب ہے۔ انیس رفیع کے افسانے اکثر داخلی خودکلامی اور بیانیہ منظرکشی (Descriptive Narration) کے حسین امتزاج سے مزین ہوتے ہیں۔ ”سوکافا“ میں بھی اس کی جھلک ملتی ہے۔ یہاں راوی کا ذہنی اضطراب، سوالیہ انداز اور تجریدی طرزِ بیان قاری کو متن میں بہا لے جاتا ہے۔ افسانے کا ہر کردار اور مقام کی علامتی حیثیت مسلم ہے۔ مثلاً ’زالونی میٹ‘ جو مصنوعی اور سطحی دنیا کا استعارہ ہے جہاں ہر چیز بے سبب اور بے معنی ہے۔ ‘برگوہائیں ‘ جو ایک باغی روح اور قبائلی ورثے کی محافظ ہے، مردہ ضمیر فروشوں سے اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ ‘سچدیوا’ سائنسی ترقی اور جدیدیت کی نمائندگی کرتا ہے لیکن وہ خود بے اختیار اور حالات کا مارا ہے۔ اور ‘راما سوامی’ جو اقتدار، نوآبادیاتی ذہنیت اور طاقت کا استعارہ، جو انسانوں کو لکڑیوں کی طرح جمع کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح افسانہ ”کاٹھ کے پتلے“ میں دکان، کاٹھ کی بنی ہوئی چیزوں کا استعارہ ہے، جو ماضی کے ثقافت، اقدار، اور تاریخی ورثے کی نمائندگی کرتی ہیں۔ لیکن اب یہ تمام اشیا تجارت کا حصہ بن چکی ہیں، گویا ہمارے اقدار، تہذیب، اور ورثے بھی منافع کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں۔ نیز یہاں ہر چیز لکڑی سے بنی ہوئی ہے، جو جمود، بے حسی اور غیر متحرک قوم کی علامت ہے۔ مثلاً چوکھٹ، دروازہ اور کھڑکی جو روایات اور قدیم اقدار کی علامتیں ہیں، جنھیں جدید دنیا میں نظرانداز کیا جا رہا ہے۔ کاٹھ کی رادھا اور کرشن، جذبات اور روحانیت کی نمائندگی کرتے ہیں، مگر بازار میں بکتے ہیں، یعنی محبت اور عقیدت بھی ایک تجارتی شے بن چکی ہے۔ اسی طرح لکڑی کا تاج محل اس بات کی علامت ہے کہ عظیم تاریخی ورثہ بھی اب محض دکھاوے کی چیز بن کر رہ گیا ہے۔ کاٹھ کا چرخہ گاندھی جی کے اصولوں اور اہنسا کا استعارہ ہے۔ آج کا صارفی سماج اسے بھی تجارتی مقصد کے لیے استعمال کرنے لگا ہے۔ کاٹھ کا کھڑاؤں جو مذہبی عقیدت اور عدم تشدد کے فلسفے کی علامت ہے، لیکن آج اسے بھی تشدد اور قتل کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔
انیس رفیع کے افسانے صرف واقعات کا بیان نہیں، ایک عہد کی دستاویز ہیں۔ ان میں اپنے دور کی چھاپ صاف نظر آتی ہے۔ وہ جدید سماجی، سیاسی اور نفسیاتی مسائل کو گہرے علامتی اور حقیقت پسندانہ اسلوب میں پرو کر اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ ان کے کردار زمان و مکاں کا استعارہ بن جاتے ہیں۔ اس زاویے سے دیکھا جائے تو ان کے افسانوں میں ارضیت پسندی کی جھلک بھی واضح طور پر دکھائی دیتی ہے جو نہ صرف موضوعاتی سطح پر نمایاں ہے بلکہ اس کا اظہار ان کی زبان، بیان، لفظیات اور کرداروں کی ذہنی ساخت کے ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ ”گدا گر سرائے“، ”اندر قلعہ“ اور”کہا لبیک ہجو نے“ ایسے افسانے ہیں جہاں بنگال اور بہار کی مٹی کی خوشبو رچی بسی ہے۔ وہ یہاں کے باسیوں کی روزمرہ زندگی، وہاں کے بول چال، کھان پان اور تہذیبی رنگوں کو بڑی چابک دستی سے اپنے افسانوں کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ ملازمت کے سلسلے میں ان کا خاصا وقت آسمام اور ناگالینڈ میں بھی گزرا ہے، جس کے اثر ات ان کے بعض افسانوں میں بھی جھلکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ اقتباس دیکھیں:
"دروازہ کھل گیا ہے۔ میرے سرہانے کھڑی ہے۔ قبائلی لڑکی مس برگوہائیں۔ چہرے پر جلال وتمکنت۔ تم کیا کیا سوچ رہی ہوگی۔ رات کا آخری پہر۔ کمرے میں نیم عریاں بدمست قبائلی خاتون۔ آنکھ لگنے سے قبل اس کے لیے جاگی ہوئی شہوت۔ کہاجاتا ہے برگوہائیں کا تعلق اس آہوم قبیلے سے ہے جس نے تقریباً سات سو سال تک اس شمال مشرقی خطے پر حکومت کی تھی… لنچ کے دوران اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ آہوم قبیلہ کی ”سوکاپھا“ ہے جس نے اپنی رعایا کی حفاظت کے لیے وحشی درندوں سے لیکر شہری شیروں تک سے ٹکر لی تھی۔ دراصل یہ ”سوکاپھا“ سات صدیوں کے ٹکراؤ کی کہانی ہے۔ جب جب رعایا درد سے کراہتی ہے تب تب ”سوکاپھا“ وارد ہوتی ہے۔ میں نے اس وقت برگوہائیں کی باتوں کو Ethnic برتری کی لن ترانی پر محمول کیا تھا۔
(افسانہ: سوکافا)
افسانہ ”قبائلی“، ”سوکافا“ اور”لاہے لاہے رفتہ رفتہ“ میں شمال مشرقی ہندستان کے قدرتی مناظر، قبائلی رسومات اور ان کے طرزِ حیات کو اس انداز سے پیش کیا گیا ہے کہ قاری کے سامنے ایک جیتی جاگتی تصویر ابھر آتی ہے۔ یہاں پہاڑ نہ صرف ایک جغرافیائی مظہر ہے بلکہ ایک ماورائی علامت بھی ہے، جو کردار کی داخلی جدوجہد کی نمائندگی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ اقتباس دیکھیں:
”Kidnapping کا کیس نہیں ہے صاحب۔ یہ تو بیہو ناچ کا کیس ہے۔ ناچ سے کوئی لڑکا لڑکی کو لے جاتا ہے تو وہ اپنی بستی میں نہیں رہ سکتا۔ کہیں اور رہتے ہیں۔ پھر آجائے گا دو چار مہینے میں۔ بیاہ کر کے یا چھوڑ کے۔“
تو لڑکی والے نے پولس میں رپورٹ درج نہیں کرائی۔ کم از کم بستی کی پنچایت سے ہی کوئی Action ہونا چاہیے تھا اتنی بڑی بات ہو گئی اور لگا کچھ ہوا ہی نہیں۔“
نہیں صاحب! یہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ دونوں خوش ہوں گے تو ساتھ رہیں گے نہیں تو اپنے اپنے گھر لوٹ آئیں گے۔ اس میں پولس پنچایت کا کیا کام۔“ عجیب رسم تھی۔ بہت دیر تک میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔
(افسانہ: لاہے لاہے، رفتہ رفتہ)
انیس رفیع کے طرزِ تحریر کی ایک اور خصوصیت ان کے مکالمے، کرداروں کا لب و لہجہ، اور مخصوص اصطلاحات ہیں، جو بیانیے میں شامل ہوکر کہانی کو حقیقت کے قریب کر دیتی ہیں۔ اکثر افسانے کا عنوان ہی مقامی لفظیات پر مشتمل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ”پوتول دی“ (بنگالی میں آپا کو دیدی کہتے ہیں اس لیے نام کے بعد مختصراً ‘دی’ جوڑ دیتے ہیں)، ”بھگ جگنی“ (عام طور پر بہار میں مادہ جگنو کو کہا جاتا ہے)، ”سوکافا“ (یا سوکاپھا: اسمیہ کی اہوم سلطنت کے پہلے راجا کا نام ہے)، ”لاہے لاہے، رفتہ رفتہ“ (لاہے لاہے اسمیہ فقرہ ہے جس کا مطلب رفتہ رفتہ ہوتا ہے) وغیرہ۔ اسی طرح ان کے دیہی پس منظر پر مبنی افسانوں میں کردار عام فہم زبان میں بات کرنے کے بجائے دیہی لب و لہجے میں گفتگو کرتے ہیں۔ مثلاً یہ اقتباس دیکھیں:
”کاہے بھاگ رہا ہے اس کے پیچھے۔ بھڑکی بھینس ادھر ادھر سینگ مار کر واپس ہوگی۔ چل ادھر آ پیٹھ کے گھموری پھوڑ دے— ”چرواہا گھموری پھوڑتی بھگ جگنی کی کانکھ سے جھانکتی ہوئی چھاتی کو ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا۔ بھگ جگنی نے اپنی کھلی ہوئی پیٹھ اس کی طرف کر دی۔ اور وہ چکو مکو بیٹھ کر اس کی پیٹھ کھجلانے لگا۔ گھموریاں اور سلگ کر لال ہو گئیں۔ وہ زور زور سے اپنے ناخن دبا دبا کر اس کی پیٹھ کھجانے لگا۔ گھموریاں کچ کچ پھوٹنے لگیں۔ لہو لہان ہو گئی پیٹھ— پلٹ کر بولی، ”ذرا زور سے کھکور، اور زور سے۔ اب ادھر چھاتی پر۔ گھموری میری جان کی دشمن ہے۔ پسینہ چھوٹا نہیں کہ بجبجا کر پیٹھ، چھاتی، کمر، ران پر میلہ لگا دیتی ہے۔“ (افسانہ: بھگ جگنی)
یہ مقامی بول چال نہ صرف بیانیے میں ایک مستند فضا پیدا کرتے ہیں بلکہ قاری کو براہ راست کہانی کے ماحول میں لے جاتے ہیں۔
انیس رفیع کی افسانہ نگاری کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ وہ اپنے دور کے اجتماعی اور انفرادی شعور کا نہایت باریک بینی سے مشاہدہ و مطالعہ کرتے ہیں اور انھیں افسانوں میں اس طرح سمو دیتے ہیں کہ قاری خود کو کردار کے محسوسات کا حصہ سمجھنے لگتا ہے۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ان کے افسانے اپنے عہد اور علاقے کی خارجی اور داخلی صورتِ حال کو منعکس کرے۔ کردار، جذبات، خواب، مسائل اور تجربات سب عصری حقائق کی بنیاد پر تخلیق ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے افسانے وقت کے زندہ دستاویز معلوم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ”الہ دین لیمپ اور عطر کی پیٹی“ میں مذہب، ثقافت، اور رسم و رواج کے ساتھ ایک مخصوص طبقے کی نفسیات بھی ابھاری گئی ہے۔ خاص طور پر نماز کے دوران اخبارات بچھانے کے معاملے میں بھولا کی کش مکش، جو اس کی مذہبی حساسیت اور فطری معصومیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اسی طرح، امام صاحب اور نماز کی ’شفٹوں ‘ کا ذکر ایک دل چسپ زمینی حقیقت کو نمایاں کرتا ہے، یعنی شہر میں عبادت کا وہ رنگ ڈھنگ جو دیہات سے مختلف ہے۔
اسی طرح افسانہ ”درآید“ باطنی اضطراب اور خوف، نیز حقیقت اور وہم کے درمیان الجھن کی عکاسی کرتا ہے۔ یہاں عنوان ہی بامعنی ہے، کہ یہ کسی شے یا خیال کے داخل ہونے، سرایت کرنے اور ذہنی خلل کا باعث بننے کی علامت ہے۔ یہاں عصری حسیت Contemporary Sensibility) کا ایک گہرا اور متنوع اظہار ملتا ہے، جو جدید انسان کی نفسیاتی کش مکش، سماجی بےچینی، اور ذہنی اضطراب کی علامتی اور استعاراتی ترجمانی کرتا ہے۔ افسانے کا مرکزی کردار ایک ایسے ذہنی الجھاو کا شکار ہے جسے وہ دوسروں کے ساتھ بانٹنے سے قاصر ہے۔ یہ کیفیت آج کے انسان کے اجتماعی شعور اور داخلی انتشار کی نمائندہ ہے۔ اس کی فریج میں کچھ ایسا بند ہے جس کا وہ اظہار نہیں کر سکتا، مگر وہ اس سے خوف زدہ ضرور ہے۔ جدید دور میں بے نام خدشات، وجودی اضطراب اور ذہنی دباؤ عام ہو چکے ہیں، اور انیس رفیع ایسے احساسات کی عمدہ تصویر کشی کرتے ہیں۔
فن کار کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ فن میں عصر ی حسیات کو برتے کہ تخلیقی عمل میں یہ ایک اہم پہلو ہوا کرتا ہے۔ انیس رفیع اس اصول کے سچے پابند نظر آتے ہیں۔ وہ افسانوں میں ایسی فضا خلق کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو قاری کو جذباتی اور فکریاتی سطح پر متحرک کر سکے۔ ان کی یہ کوشش ان کے پہلے افسانے ”شاہکار“ (1969ء) میں منعکس ہوتی ہے۔ افسانے کا بنیادی موضوع فن کی تلاش، تخلیقی کرب، اور وقت کے شکنجے سے نجات پانا ہے۔ ستنام سنگھ ایک ایسا فن کار ہے جو حقیقی ”شاہکار“ تخلیق کرنے کی جستجو میں ہے، مگر ہر بار ایک خلا میں گم ہو جاتا ہے۔ یہ خلا صرف کینوس پر نہیں، اس کی روح میں بھی موجود ہے۔ افسانے کا ایک اہم پہلو وقت کا تصور ہے، جو ایک بے رحم قوت کے طور پر فن کار پر حاوی نظر آتا ہے۔ وقت کے ہاتھوں ستنام سنگھ کی بے بسی اور اس کے فن کی ناتمامی افسانے کی نفسیاتی گہرائی کو بڑھاتی ہے۔
اگرچہ انیس رفیع کی افسانہ نگاری نئی جدیدیت، نادر علامتی اظہار اور فکری وسعت کا ا علا نموہے، لیکن بعض ناقدین کے نزدیک ان کے افسانے دوسرے جدیدیوں کی طرح ہی ابہام، پیچیدہ بیانیے، تجریدی عناصر، غیر روایتی کردار سازی اور کہانی پن کی کمی کے باعث ترسیل میں مشکلات پیدا کرتے ہیں اور وہ اسے ان کے افسانوں کی کم زوریاں گردانتے ہیں۔ تاہم، یہ کم زوریاں ہی بعض اوقات ان کی اصل قوت بھی بن جاتی ہیں، کہ یہی عوامل ان کے افسانوں کو ایک انوکھا ادبی رنگ اور جمالیاتی آہنگ عطا کرتے ہیں۔ درحقیقت، یہی وہ عوامل ہیں جو انیس رفیع کو اردو افسانے کی دنیا میں ایک مستند اور منفرد مقام بخشتے ہیں۔
***
صاحب مقالہ کی گذشتہ نگارش:غضنفر کے افسانوں میں عصری مسائل

انیس رفیع : نئی جدیدیت سے عصری حسیت تک
شیئر کیجیے