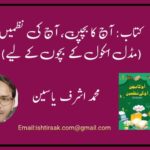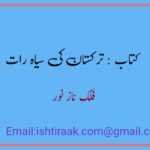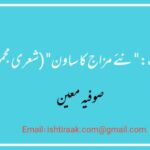زبان محض اظہار کا ذریعہ نہیں، یہ انسانی تہذیب و شعور کی سانس ہے۔ یہ وہ عطیۂ ربانی ہے جو خیالات کو لفظوں کا لباس پہنا کر دل سے دل تک پہنچاتی ہے۔ زبان ہی سے رشتے بنتے اور ٹوٹتے ہیں، محبت کے چراغ جلتے ہیں اور نفرت کے طوفان بھی اٹھتے ہیں۔ کبھی یہ امن و اخوت کا پیغام سناتی ہے، تو کبھی بغاوت کے نعرے بلند کرتی ہے؛ کبھی حکمرانوں کے دربار میں وفاداری کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں اور کبھی اسی زبان سے طغیانِ وقت کے خلاف للکار سنائی دیتی ہے۔
اردو زبان و ادب کی تاریخ اس حقیقت کی جیتی جاگتی گواہ ہے کہ یہ صرف سخن کا زیور نہیں بلکہ حریتِ فکر اور آزادیِ عمل کی علمبردار بھی رہی ہے۔ برصغیر کی آزادی کی جدوجہد میں اردو نے محض ایک زبان کے طور پر نہیں بلکہ ایک متحدہ قومی شعور کے روپ میں کردار ادا کیا۔ افسوس کہ بعض متعصب ذہنیتیں اور حکومتی رویے اس کردار کو کم کرنے کی کوشش کرتے رہے—اردو کے ماننے والوں کو غدار، بغاوتی یا شدت پسند کہہ کر بدنام کیا گیا، اور زبان کو مٹانے کی تدبیریں کی گئیں —لیکن تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ سچائی کبھی فنا نہیں ہوتی۔
1857ء کی پہلی جنگِ آزادی سے لے کر آج تک، ہر دور میں اردو نے ظلم و جبر کے مقابل عوامی ضمیر کو بیدار کیا ہے۔ سرسید احمد خاں، شبلی نعمانی اور مولانا حالی نے تعلیم و شعور کا چراغ جلایا، اکبر الہ آبادی اور علامہ اقبال نے خودی، عمل اور حریتِ فکر کا سبق یاد دلایا، منشی پریم چند نے سامراجی اور سرمایہ دارانہ جبر میں پسے عوام کے دکھ لکھے، چکبست نے حب الوطنی کے نغمے گائے، اور جوش، فیض، فراق، مجاز اور کیفی جیسے شعرا نے آزادی کے خواب کو لفظوں میں ڈھال کر ایک پوری نسل کو بیدار کیا۔
ترقی پسند تحریک کی بنیاد 1935ء میں لندن کے ایک ریستوران میں رکھی گئی جہاں سجاد ظہیر، ملک راج آنند، جیوتی گھوش، پرمود سین گپتا اور محمد دین تاثیر نے بیٹھ کر اس کے خدوخال طے کیے۔ بعد میں اس تحریک کا پہلا منشور شائع ہوا، جس میں کہا گیا:
”رفیقان قلم! موت کے خلاف زندگی کی ہم نوائی کیجئے، ہمارا قلم، ہمارا فن اور ہمارا علم ان طاقتوں کے خلاف رکنے نہ پائے جو موت کو دعوت دیتی ہیں۔ جو انسانیت کا گلا گھونٹی ہیں، جو دولت کے بل پر حکومت کرتی ہیں، جو سرمایہ داروں اور زر پرستوں کی آمریت قائم کرتی ہیں اور فاشزم کے مختلف روپ دھار کر سامنے آتی ہیں اور کئی وہ طاقتیں ہیں جوم معصوم انسانوں کا خون چاہتی ہیں۔“ (1)
اس منشور کا مقصد ادب کو عوام کے مسائل اور آزادی کی تحریک کے ساتھ جوڑنا تھا۔ روٹی، کسان کی محنت، مزدور کا پسینہ، عورت کی عزت، غریب کی بھوک—یہ سب ادب کے موضوعات ہونے چاہیے تھے، تاکہ انقلابی شعور پروان چڑھے۔ لندن میں ہوئے انجمن کے باقاعدہ جلسے میں یہ بات کہی گئی تھی. لندن میں جو پہلا منشور تیار ہوا اس میں انگریزی سامراج سے مورچہ لینے اور ہندستان کو آزاد کرانے کی طرف واضح طور پر اشارہ تھا جو کچھ اس طرح تھا ”ہمارا عقیدہ ہے کہ ہندوستان کے نئے ادب کو ہماری موجودہ زندگی کی بنیادی حقیقتوں کا احترام کرنا چاہئے اور وہ ہے ہماری روٹی کا، بدحالی کا، ہماری سماجی پستی اور سیاسی غلامی کا سوال، ہم اس وقت ان مسائل کو سمجھیں گے اور ہم میں انقلابی روح بیدار ہو گی”۔(2)
اپریل 1936ء میں لکھنو میں ترقی پسند ادبی تحریک کی پہلی کل ہند کانفرنس منعقد ہوئی جس کے اعلان نامے میں یہ باتیں پیش کی گئی تھیں: ”ہمارے ملک میں بڑی بڑی تبدیلیاں ہورہی ہیں، پستی اور رجعت پسندی کو اگرچہ موت کا پروانہ مل چکا ہے لیکن وہ ابھی تک معدوم نہیں ہوئی ہیں۔ نت نئے روپ بدل کر یہ مہلک زہر ہمارے تمدّن کے ہر شعبے میں سرایت کرتا جارہا ہے۔ اس لیے ہندوستانی مصنفین کا فرض ہے کہ ملک میں جو ترقی پزیر رجحانات ابھر رہے ہیں ان کی ترجمانی کریں اور ان کی نشو نما میں پورا حصہ لیں“(3)
اعلان نامہ کے آخر میں اس بات پر زور دیا گیا تھا: ”ہم ان تمام آثار کی مخالفت کریں گے جو ہمیں لاچاری، سستی اور توہم پرستی کی طرف لے جارہے ہیں۔ ہم ان تمام قوتوں کو جو ہماری قوت تنقید کو ابھارتی ہیں اور رسموں اور اداروں کو عقل کی کسوٹی پر رکھتی ہیں تغیر اور ترقی کا ذریعہ قبول کرتے ہیں۔“ (4)
اسی کانفرنس میں منشی پریم چند نے اپنے صدارتی خطبے میں کہا تھا: ”ہماری کسوٹی پر وہ ادب کھرا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو۔ حسن کا جوہر ہو، تعمیر کی روح ہو، زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو، جو ہم میں حرکت، ہنگامہ اور بے چینی پیدا کرے، سلائے نہیں کیوں کہ اب زیادہ سونا موت کی علامت ہوگی۔"(5)
حسرت موہانی نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا: "ہمارے ادب کو قومی آزادی کی تحریک کی ترجمانی کرنی چاہیے۔ اسے سامراجیوں اور ظلم کرنے والے امیروں کی مخالفت کرنا چا ہیے۔ اسے مزدوروں، کسانوں اور تمام مظلوم انسانوں کی طرف داری اور حمایت کرنا چاہیے۔ اس میں عوام کے دکھ سکھ، ان کی بہترین خواہشوں اور تمناؤں کا اظہار اس طرح کرنا چا ہیے جس سے ان کی انقلابی قوت میں اضافہ ہو اور وہ متحد و منظم ہو کر اپنی جدوجہد کو کامیاب بنا سکیں۔“(6)
مارچ 1938ء میں جب آلہ آباد میں دوسری مرتبہ بڑی کانفرس ہوئی جس میں یوپی، بہار اور پنجاب سے ادبا نے شرکت کی تھی اس کانفرنس میں جواہر لال نہرو نے دوران تقریر کہا تھا:
”آنے والے انقلاب کے لیے ملک کو تیار کرنا؛ اس کی ذمہ داری ادیب پر ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کے مسئلوں کو حل کیجیے، انھیں راستہ بتائیے لیکن آپ کی بات آرٹ کے ذریعہ ہونی چا ہے نا کہ منطق کے ذریعے۔ آپ کی بات انسان کے دل میں اترنی چاہیے۔“(7)
ٹیگور نے الہ آباد کی کا نفرنس میں جو پیام نو جوانوں کے لیے بھیجا تھا اس میں یہ بات بھی کی گئی تھی:
”آج ہمارا ملک ایک لق و دق صحرا ہے جن میں شادابی اور زندگی کا نام ونشان نہیں ہے۔ ملک کا ذرہ ذرہ دکھ کی تصویر بنا ہوا ہے۔ ہمیں اس غم و اندوہ کو مٹانا ہے اور از سر نو زندگی کے چمن میں آبیاری کرنا ہے۔ ادیب کا فرض یہ ہونا چاہیے کہ ملک میں نئی زندگی کی روح پھونکے، بیداری اور اور جوش کے گیت گائے، ہر انسان کو امید اور مسرت کا پیغام سنائے اور کسی کو ناامید اور ناکارہ نہ ہونے دے۔“(8)
دوسری کل ہند کانفرنس دسمبر 1938 میں کلکتہ میں منعقد ہوئی۔ اس کے بعد 1936 میں لکھنؤ سے ترقی پسند ادیبوں کا ایک رسالہ” نیا ادب" کے نام سے شائع ہونے لگا۔ اس رسالے نے تھوڑے ہی عرصے میں اپنا ایک معیار قائم کرلیا۔ مارچ 1940ء میں ’آزادی کی نظمیں‘ کے عنوان سے ایک مجموعہ حلقہ ادب لکھنؤ سے شائع ہوا۔ اس کے مرتب سبط حسن نے اس مجموعے کے بارے میں لکھا تھا: ”آزادی کی نظموں کا زیر نظر مجموعہ صرف نظموں کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ احساس غلامی کے ارتقا کی تاریخ ہے اور مجھے خوشی ہے کہ مرتب نے انتخاب کی بنیاد قومی زندگی کی حقیقتوں پر رکھی ہے۔ اس انتخاب سے اس دعویٰ کی بھی تائید ہوتی ہے کہ ادب اور زندگی میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اگر ان نظموں کو غور سے پڑھا گیا تو نہ صرف آزادی کے تصور کا تدریجی ارتقاء واضح ہو جائے گا بلکہ یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ آج ہم کس منزل پر ہیں اور ہمارے رجحانات کیا ہیں اور ہماری آئندہ منزل کیا ہوگی۔“(9)
یہ مجموعہ حکومت برطانیہ کی طرف سے بہت جلد ضبط کر لیا گیاتھا۔ تیسری کل بند کا نفرنس دہلی میں مئی 1942ء کو منعقد ہوئی جب پوری دنیا پر دوسری جنگ عظیم کے بادل منڈلا رہے تھے۔ فاشزم کے خلاف اور جمہوریت کی بقا کے لیے ترقی پسند ادیبوں کی آوازیں اٹھ رہی تھیں۔ چنانچہ اس کانفرنس میں جو منشور تیار ہوا اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ”ہم بر طانوی سامراج کے اس رویے کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ وہ ان نازک حالات میں ہمارے وطن کو آزادی دینے کے لیے تیار نہیں۔“(10)
دہلی کی کانفرنس میں جنگ کے متعلق جو باتیں کی کی تھیں اس کی حمایت میں جوش اور ساغر کے بیانات بھی اخباروں کی سرخی بن چکے تھے۔ ”ہمارا عملی سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ ہماری زندگی فن، شعر اور علم و ادب سے وابستگی رکھتی ہے لیکن باوجود تخلیقی و تعمیری جدوجہد کے ہمارا بھی ایک سیاسی عقیدہ ہے جسے ہم شاعر اور ادیب اپنی جانوں سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ ہندوستان کی مکمل آزادی اور ایک سوشلسٹ نظام حکومت ہمارا منتہائے خیال ہے……………… سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک غیر ملکی، غیر ذمہ دار اور مطلق العنان نوکر شاہی ہماری جلیل القدر قوم کو وطن کی مخالفت کا موقع نہیں دیتی۔ جو ہمارے سیاسی رہنماؤں کو یہ عظیم فریضہ سونپنا نہیں چاہتیں۔ جو انہیں گرفتار کر کے ہندوستانی عوام کو مشتعل و برانگیختہ کرتی ہے۔ ہم کامل یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ملک میں تخریب کی تمام برباد کن حرکتیں برطانوی حکومت کی اشتعال انگیزی اور جابرانہ پالیسی کا نتیجہ ہیں۔“ (11)
اسی وقت مجاز نے اپنی نظم ’آہنگ نو‘ لکھی اور اخبارات میں بیان شائع کرا دیا تھا جس کا ایک اقتباس یہ ہے۔ ”ہمارے نغموں کو آج دوبارہ وطن کی فضاؤں میں گونجنا چاہیے تا کہ اتحاد، اعتماد، سرفروشی اور حیرت کے جذبات سے معمور ہو کر ہم اپنے راستے سے ہر اس رکاوٹ کو ہٹا دیں جو اندھے سامراجی راہ میں حائل کرتے ہیں اور تمام دنیا کی عوام کے ساتھ مل کر اس جنگ آزادی میں اس طرح شریک ہوں جو ہماری عظیم المرتبت قوم کے شایان شان ہے۔“ (12)
خلیل الرحمن اعظمی نے لکھا ہے۔’مخدوم کا ترانہ‘ یہ جنگ ہے جنگ آزادی‘ اور نظمیں ’اندھیرا‘ سپاہی ” اس دور کی یادگار چیزیں ہیں جو ترقی پسند تحریک کی ترجمانی کرتی ہیں۔ کرشن چندر کا افسانہ’’ موبی‘ اور’ ایک نافسطائی کی ڈائری‘، خواجہ احمد عباس کا ڈرا مہ ’یہ امرت ہے‘، سردار جعفری کا ڈرامہ یہ کس کا فون ہے‘ اس کی عکاس ہیں۔ اختر انصاری نے ہولناکیوں اور فا شزم کی مخلافت میں بہت سی نظمیں لکھیں اور انھیں ’روح عصر‘ کے نام
سے شائع کیا۔‘ (13)
ترقی پسند ادیبوں نے اپنی شعری اور نثریاقران تصنیفات سے نا صرف اردو زبان و ادب کو باقی رکھا بلکہ ادب کو ادب برائے ادب کے ساتھ ادب برائے زندگی کے سانچے میں ڈھال دیا جس میں مظلوموں کی فریادیں، بیواؤں کا سہاگ، فاقہ کشی، بے روزگاری، اور نوجوان نسل کے مسائل کے علاوہ بھی بہت کچھ شامل ہے۔ ان شعرا نے اپنی نظموں اور غزلوں سے نوجوان نسل کے اندر خود اعتمادی، بلند ہمتی اور انگریزی سامراج سے مقابلہ کرنے کا جذبہ پیدا کیا۔ ہندو مسلم اتحاد کی بقا کے گیت گائے۔ لوگوں کے درمیان محبت قائم کرنے کا درس دیا۔
یہ تحریک محض ایک ادبی رجحان نہیں تھی بلکہ آزادی کے خواب کو لفظوں میں ڈھالنے کا عمل تھی۔ اس نے ثابت کیا کہ قلم کی طاقت بندوق سے کم نہیں، اور کہ ادب جب عوام کی نبض سے جڑ جائے تو وہ انقلاب کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔
حواشی و مآخذ
اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک از خلیل الرحمٰن اعظمی۔ ص 30، 31
اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک از خلیل الرحمٰن اعظمی۔ ص 40
اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک از خلیل الرحمٰن اعظمی۔ ص 41
نیا ادب، جنوری فروری 1941
روشنائی از سجاد ظہیر۔ص 112
اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک از خلیل الرحمٰن اعظمی۔ ص 54
اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک از خلیل الرحمٰن اعظمی۔ص 56
آزادی کی نظمیں مرتبہ سید حسن ص 11
روشنائی از سجاد ظہیر ص 287
اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک از خلیل الرحمٰن اعظمی۔ ص 65، 66
نیا ادب سہ ماہی 1943، شمارہ 1
اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک از خلیل الرحمٰن اعظمی۔ ص 69
***
Abul Faiz
Contact +91 9540879535
Email abulfaiz.h@gmail.com
***
ابوالفیض معینی کی گذشتہ نگارش:
شیئر کیجیے